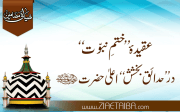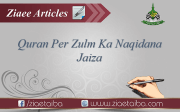حدیث ’’اصحابی کالنجوم‘‘ کی فنی حیثیت
سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا سلفاً و خلفاً یہی عقیدہ رہا ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں، ثقہ ہیں، ثبت ہیں، ان کی اقتداء، ان کی پیروی، ان سے محبت، ان کا ذکر خیر سے کرنا، ان کی بارگاہوں میں گستاخی نہ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی دینی اور شرعی حیثیت کو اپنے ارشادات طیبہ کے ذریعہ بہت سے مقامات پر واضح فرمایا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے ان کی اقتداء و پیروی کو لازمی قرار دیا ہے۔ چونکہ ان کی اقتداء و پیروی کرنا اور ان کو اپنا ہادی و رہنما ماننا بحیثیت مسلمان ہر ایک کے لیے لازم و ضروی ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ان شخصیات کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہ کون سی مقدس جماعت ہے۔ ان کے اندر وہ کون سی ایسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کے ستارے قرار دیا۔ ان کی اقتدا و پیروی کرنے کا حکم صادر فرمایا، اکابر امت، ائمہ کرام اور اسلاف نے انہیں ہمیشہ اپنا مقتدا تسلیم کیا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ؎
جس مسلماں نے دیکھا انہیں اک نظر
اُس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام
اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول
نجم ہیں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی
اس عظیم مقام و مرتبہ کے حامل جو افراد ہیں اُن کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے یہ جانا جائے کہ یہ وصفِ صحابیت ہے کیا؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کون لوگ اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں؟ کن لوگوں کو یہ مقام حاصل ہوا؟ جن لوگوں کو یہ مقام حاصل ہوا ہم انہیں کِن اصولوں کی روشنی میں شناخت کریں؟ قرآن و حدیث اور اقوال اسلاف کی روشنی میں صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے فضائل و مناقب کیا ہیں؟
صحابی کا لغوی معنیٰ:۔
صحابی ’’الصحبۃ‘‘ سے مشتق ہے۔ یعنی ہر وہ شخص صحابی کہلاتا ہے کہ جس نے کسی دوسرے کی تھوڑی یا زیادہ مدّت تک صحبت اختیار کی ہو اور اُس کے ساتھ رہا ہوں۔ جیسے مکلم، مخاطب، رضا رب۔ یہ مکالمہ، مخاطبہ اور ضرب سے مشتق ہیں لہٰذا تھوڑی یا زیادہ گفتگو کرنے والے شخص کو مکلم کہا جائے گا۔ صحابی کے اسی لغوی معنی کے اعتبار سے اُس شخص کو بھی صحابی کہا جائے گا کہ جس نے دن کے ایک لمحے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو۔ امام سخاوی نے فرمایا کہ لغوی اعتبار سے صحابی کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوگا کہ جس نے اتنی تھوڑی مدّت بھی صحبت اختیار کی ہو کہ جس پر صحبت کا اطلاق ہوسکے۔ لہٰذا جن لوگوں کی صحبت بہت طویل اور جن کی مجالست بہت کثیر رہی ہو وہ تو بدرجۂ اولیٰ صحابی ہوں گے۔ [1]
علمائے اصول کے نزدیک صحابی کی تعریف:
امام ابو الحسین نے ’’معتمد‘‘ میں صحابی کی تعریف یوں کی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ طویل زمانے تک اتباع و پیروی کے طور پر اور ان سے اخذ و تعلیم کے طور پر رہا ہو اُسے صحابی کہیں گے۔ لہٰذا جن لوگوں کی مجالست تو طویل تھی لیکن اتباع کا قصد نہ تھا یا مجالست طویل تو نہ تھی مگر اتباع کا قصد تھا تو ایسے لوگ صحابی نہ کہلائیں گے۔
محدثین کے نزدیک صحابی کی تعریف:۔
ابو المظفر سمعانی کےحوالے سے ابن صلاح نے یہ قول نقل کیا ہے کہ اصحاب حدیث لفظ صحابہ کا اطلاق ہر اُس شخص پر کرتے ہیں جس نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی روایت کی ہو اگرچہ وہ ایک حدیث یا ایک کلمہ ہی کیوں نہ ہو۔ صحابی کے اس اطلاق کے دائرے میں مزید وسعت دیتے ہوئے یہ اصحاب حدیث فرماتے ہیں کہ جس نےانہیں ایک نظر ہی کیوں نہ دیکھا ہو وہ بھی صحابی کہلائے جانے کا استحقاق رکھتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام رفیع اس بات کا مقتضی ہے کہ ہر اُس شخص کو صحابی کا خطاب دیا جائے کہ جس نے آقا کو دیکھا ہو۔
تابعین کرام کے حوالے سے بھی کتابوں میں صحابی کی مختلف تعریفات ملتی ہیں:
حضرت سعید بن مسیّب فرماتے ہیں کہ صحابی اُسے کہیں گے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک یا دو سال گزارے ہوں اور ان کے ساتھ ایک یا دو غزوات میں حصہ لیا ہو۔
امام واقدی نے فرمایا کہ میں نے اہل علم کا یہ قول دیکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے آقا کو دیکھا ہو اس حال میں کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ گیا ہو، اسلام لے آیا ہو، امور دینیہ کی سمجھ اُس کے اندر پیدا ہوگئی ہو اور وہ شریعت کو پسند کرتا ہو تو وہ ہمارے نزدیک صحابی ہے اگرچہ دن کی ایک گھڑی ہی میں اس نے آقا کی زیارت کیوں نہ کی ہو۔ یعنی ان کے نزدیک صحابی ہونے کے لیے بالغ ہونا، مسلمان ہونا، مسائل شرعیہ کی فہم کا ہونا اور مذہب کا پسندیدہ ہونا شرط ہے۔
صحابی کی مذکورہ تمام اصطلاحی تعریفات کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن حجر عسقلانی نے ایک ایسی جامع تعریف فرمائی ہےکہ جس پر کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا اور وصفِ صحابیت سے متصف ہونے کا استحقاق رکھنے والے تمام حضرات اُس میں شامل ہوجاتے ہیں۔
صحابی کی صحیح تعریف:۔
جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اُن کی حیات طیبہ میں حالت ایمان میں ملاقات کی ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو تو اسے صحابی کہتے ہیں۔
اس تعریف کی رو سے وہ شخص بھی صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں شامل ہوجائے گا کہ جس کی مجالست آقا کے ساتھ طویل رہی ہو، وہ بھی داخل ہوگا کہ جس کی کم رہی ہو۔ وہ بھی داخل ہوگا کہ جس نے ان سے روایت کی ہو یا روایت نہ کی ہو، آقا کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ وہ لوگ بھی اس زمرے میں شامل ہوجائیں گے کہ جنہوں نے محض ایک ہی نظر دیکھا اور لمبی مجالست نہ رہی۔ اسی طرح وہ بھی صحابی کہلائے گا کہ جس نے انہیں کسی عرض عارض کی بنیاد پر نہ دیکھا ہو جیسے کے نا بینا۔
مذکورہ تعریف ایک جنس اور دو فصلوں پر مشتمل ہے ’’من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم‘‘ یہ جنس ہے جس میں مسلم و کافر، بالغ و نا بالغ ہر وہ شخص شامل ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں آقا سے ملاقات کی ہو۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جنہوں نے آقا کےوصال کے بعد اور تدفین سے پہلے آقا کو دیکھا تو وہ صحابی نہ کہلائے گا۔ جیسے ابو ذؤیب الہزلی شاعر کیونکہ اُنہوں نے آقا کو وصال کے بعد اور تدفین سے پہلے دیکھا تھا۔
’’الایمان‘‘ ایمان مذکورہ تعریف میں فصل اول کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ شخص مرتبۂ صحابیت پانے سے خارج ہو گیا کہ جس نے ایمان کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ اسی طرح وہ افراد کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء پر ایمان رکھتے تھے اور وہ اعلان نبوت سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہوگئے جیسے کہ اہل کتاب۔ یہ لوگ صحابی نہیں کہلائیں گے۔ اب رہ گئے وہ اہل کتاب کہ جنہوں نے اعلان نبوت اور نزول وحی سے پہلے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی اور اس بات پر ایمان بھی رکھا کہ وہ عنقریب مبعوث ہوں گے۔ وہ اس زمرۂ صحابہ میں شامل کیے جائیں گے کہ نہیں؟ یہ محل احتمال ہے۔ جیسے کہ بحیرہ راہب وغیرہم۔
’’مات علیٰ اسلامہ‘‘ اسلام ہی پر خاتمہ ہونے والی یہ قید اور شرط اس تاریخ میں فصل دوم کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس سے وہ لوگ صحابی ہونے سے نکل گئے کہ جو آقا کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے۔ اب رہ گئے وہ لوگ کہ جو آقا کے بعد مرتد ہوئے پھر اسلام لائے اور حالت اسلام ہی میں اُن کی موت واقع ہوئی ایسے لوگوں کو صحابی کہا جائے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں حضرت امام شافعی اور حضرت امام اعظم کا موقف یہ ہے کہ ارتداد یہ صحبت سابقہ کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے کہ قرّہ بن میسرہ اور راشعث بن قیس۔ یہ دونوں حضرات پہلے اسلام لائے پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مُرتد ہوگئے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں دوبارہ اسلام لائے۔ علامہ ابن حجر کے نزدیک ایسے لوگوں کو صحابی کے نام سےیاد کیا جائے گا۔ نیز محدثین نے اپنی مرویات میں انہیں صحابہ ہی کے نام سے درج کیا ہے۔
واضح رہے کہ یہ اختلاف اُن لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد مُرتد ہوئے اور پھر اسلام لے آئے۔ البتہ وہ لوگ کہ جن کی موت ہی ارتداد پر ہوئی وہ بالا تفاق صحابی کہلانے کے مستحق نہیں جیسے حضرت اُمِّ حبیبہ کا شوہر عبید اللہ بن حجش کہ یہ حضرت اُمِّ حبیبہ کے ساتھ اسلام لایا، اُس کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کی مگر وہاں جا کر نصرانی ہوگیا اور اسی حالت میں اُس کی موت واقع ہوگئی۔ اسی طرح عبد اللہ بن خطل اور ربیعہ بن امیہ بن خلف۔ کیا ملائکہ میں سے بھی کوئی صحابی ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی نے ملائکہ کے وصف صحابیت سے متصف ہونے کے سلسلے میں فرمایا کہ زُمرۂ صحابہ میں اُن کا داخل کرنا یہ محل نظر ہے اور اس کی وجہ بعض لوگوں نے یہ بیان کی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ جس کو امام فخر الدین رازی نے ’’اسرار النزیل‘‘ میں نقل فرمایا ہے۔ اس کے برخلاف علامہ تقی الدین سبکی نے فرمایا کہ وہ اِن کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس قول کی بنیاد پر یہ وصفِ صحابیت سے متصف کیے جاسکتے ہیں۔ بہر حال کسی فرشتے کا زُمرۂ صحابہ میں داخل ہونا یہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے۔
کیاجن صحابی ہوسکتے ہیں؟
چونکہ جن اُن اجسام ہوائیہ لطیفہ کو کہتے ہیں کہ جو مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قادر ہوتے ہیں اور جن سے حیرت انگیز افعال صادر ہوتے ہیں۔ ان میں سے مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہےکہ کیا جنّات وصف صحابیت سے متصف ہوسکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی نے راجح قول پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جنات کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا یا اُن کی زیارت کی تو وہ بلا شبہ صحابی کہلانے کے مستحق ہیں کیونکہ یہ بات قطعی اور یقینی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن و انس دونوں کی طرف مبعوث ہوئے۔
صحابی کی شناخت کے طریقے:۔
کون صحابی ہے اور کون نہیں اس کی معرفت کے مندرجہ ذیل پانچ طریقے ہیں:
۱۔ خبر متواتر سے ثبوت:
کسی صحابی کا صحابی ہونا خبر متواتر سے ثابت ہو۔ یعنی کسی کے صحابی ہونے کو اتنے لوگوں نے بتایا ہو کہ جن کا جھوٹ پر اجماع عقلاً و عادتاً محال ہو۔ ایسے لوگوں کا صحابی ہونا قطعی اور یقینی ہے جیسے خلفائے راشدین اور بقیہ عشرۂ مبشرہ۔
۲۔ خبر مشہور اور خبر مستفیض سے ثبوت:
یعنی وہ لوگ کہ جن کا صحابی ہونا خبر مشہور یا خبر مستفیض سے معلوم ہو جیسے کہ ضمام بن ثعلبہ او رعکاشہ بن خصن۔
۳۔ قول صحابی سے ثبوت:
یعنی کسی کے صحابی ہونے کے بارے میں کسی ایک صحابی نے روایت کی ہو اور بتایا ہو کہ فلاں صحابی ہے جیسے حمحمہ بن ابی حمحمہ دوسی جن کے صحابی ہونے کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے گواہی دی۔
۴۔ قول تابعی سے ثبوت:۔
کسی تابعی نے یہ خبر دی ہو کہ فلاں صحابی ہے۔
۵۔ خود اپنے قول سے ثبوت:۔
کسی عادل و ثقہ ایسے شخص نے کہ جس نے آقا کا زمانہ پایا ہو اُس نے خود اپنے بارے میں یہ خبر ہو کہ میں صحابی رسول ہوں تو اُس کی عدالت و ثقاہت اور معاصرت رسول کے ثبوت کے بعد اُسے صحابی مانا جائے گا۔
اس سلسلہ میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے ایک ایسا جامع ضابطہ نقل کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت میں کثیر افراد داخل ہوسکتے ہیں۔ یہ ضابطہ تین نشانیوں پر مشتمل ہے۔ لہٰذا اُن تین نشانیاں کی بنیاد پر کثیر افراد زُمرۂ صحابہ میں داخل ہوجائیں گے۔
۱۔ چونکہ غزوات میں صرف صحابہ کرام ہی شامل ہوتے تھے۔ لہٰذا جن کا مرتد ہونا ثابت ہوجائے انہیں چھوڑ کر بقیہ جتنے بھی لوگ جنگوں میں شامل ہوئے وہ سب صحابی ہی ہوں گے۔
۲۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے فرمایا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو اُسے آقا کی بارگاہ میں لایا جاتا۔ آقا اُس کے لیے دعا فرماتے۔ اس قول کی بنیاد پر بھی صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔
۳۔ مدینہ شریف، مکہ شریف، طائف اور اُس کے اِرد گرد کے جتنے بھی خطے ہیں اُن میں رہنے والے سارے لوگ ہی اسلام لائے اور حجۃ الوداع کے موقع پر شریک ہوئے۔ ایسی صورت میں جن لوگوں نے بھی آقا کو اس حج کے موقع پر دیکھا وہ زُمرۂ صحابہ ہی میں داخل ہونگے اگرچہ آقا نے اُن کو نہ دیکھا ہو۔
مذکورہ ضابطے سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد بلاشبہ، بہت زیادہ ہے اگرچہ ہمیں تفصیل کے ساتھ اُن کے نام اور اُن کی معیّن تعداد معلوم نہ ہو۔
صحابہ کا مقام و مرتبہ:۔
صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے بہت ہی عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ان کی عظمت و رفعت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ تمام صحابہ کرام بالا اتفاق ایسے عادل و ثقہ ہیں کہ اِن میں سے کسی کی عدالت کے سلسلہ میں نہ تو کوئی سوال کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کوئی تفتیش۔ صحابۂ کرام کے عادل ہونے اور اِن کی عدالت پر قرآن و حدیث میں بہت سے دلائل موجود ہیں اس کے ساتھ ہی ان کی عدالت اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔
عدالت صحابہ قرآن کی روشنی میں
قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اِن پاکباز ساتھیوں کی تعریف و توصیف کی گئی اور ان کی عدالت کے بارے میں بتایا گیا۔ ان میں سے چند آیات یہاں پر نقل کی جا رہی ہیں:
۱۔ مُّحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًازسِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ ج وَمَثَلُهُمْ فِىۡ الْاِنْجِيْلِقف كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَـغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا [2]
ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ تو انہیں دیکھا گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے۔ اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ اُن کی علامت اُن کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے۔ یہ اُن کی صفت توریت میں ہے اور اُن کی صفت انجیل میں۔ جیسے ایک کھیتی اُس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اُسے طاقت دی پھر دبیز ہوئی پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ اُن سے کافروں کے دل جلیں۔ اللہ نے وعدہ کیا اُن سے جو اُن میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں بخشش اور بڑے ثواب کا۔ [3]
۲۔ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗؕ اُولٰٓئِکَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ [4]
ترجمہ: اِن فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے۔ اللہ کا فضل اور اُس کی رضا چاہتے اور اللہ و رسول کی مدد کرتے۔ وہی سچے ہیں اور جنہوں نے پہلے سے اِس شہر اور ایمان میں گھر بنالیا دوست رکھتے ہیں اُنہیں جو اُن کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اُس چیز کی جو دئیے گئے اور اپنی جانوں پر اُن کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ [5]
۳۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اَاوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّاؕ لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ [6]
ترجمہ: اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں۔ اُن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ [7]
۴۔ لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا [8]
ترجمہ: بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اُس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ تو اللہ نے جانا جو اُن کے دلوں میں ہے تو اُن پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ [9]
۵۔ يٰٓـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ [10]
ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ [11]
۶۔ وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍۙ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًاؕ ذٰلِكَ الْـفَوْزُ الْعَظِيْمُ [12]
ترجمہ: اور سب نے اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ اُن کے پیرو ہوئے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ہمیشہ اُن میں رہیں یہی بڑی کامیابی ہے۔ [13]
۷۔ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا [14]
ترجمہ: اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل۔ [15]
۸۔ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ [16]
ترجمہ: تم بہتر ہو اُن سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ [17]
۹۔ وَجَاهِدُوْا فِىْ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖؕ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِىْ الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَؕ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ [18]
ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا۔ اُس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تاکہ رسول تمہارا نگہبان اور گواہ ہو اور تم اور لوگوں پر گواہی دو۔ [19]
۱۰۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى [20]
ترجمہ: تم کہو سب خوبیاں اللہ کو اور سلام اُس کے چنے ہوئے بندے پر۔ [21]
’’عبادہ الذین اصطفی‘‘ اللہ کے وہ بندے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے چُن لیا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اس سلسلہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا۔
عدالت صحابہ احادیث کریمہ کی روشنی میں:۔
جن لوگوں نے ہوش و ایمان کی حالت میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا یا آقا کی صحبت میں حاضر ہوئے پھر ایمان پر ہی اُن کا خاتمہ بھی ہوا ایسے لوگوں کی عدالت قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث کریمہ سے بھی اور اجماع امت سے بھی۔ صحابۂ کرام کی عظمت و رفعت اور فضائل و مناقب کے سلسلہ میں بہت سی احادیث کریمہ موجود ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ مقدس جماعت ہے جو تمام مسلمانوں سے افضل ہے۔ روئے زمین کے سارے ولی، غوث، قطب اور ابدال کسی ایک صحابی کے گردِ قدم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس سلسلہ میں چند احادیث کریمہ ذیل میں نقل کی جاتی ہیں:
۱۔ عن ابی سعید عن النبی۔ علیہ السلام۔ قال: لا تسبوا اصحابی، فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذھبا ما ادرک مد احدھم ولا نصیفہ۔ [22]
ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو بُرا نہ کہو کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے تو وہ اِن صحابہ سے کسی ایک کے ایک مُد کو بھی نہ پہنچے اور نہ آدھے مُد کو۔ (چار مُد کا ایک صاع ہوتا ہے ایک صاع ساڑھے چار سیر کا تو اس لحاظ سے ایک مُد ایک سیر آدھ پاؤ کا ہوا یعنی تقریباً سوا سیر)
واضح رہے کہ یہاں یہ خطاب حضرت خالد بن ولید اور اُن کے اُن ساتھیوں سے ہے کہ جو صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضرت خالد بن ولید جیسے صحابۂ کرام کا اللہ کی راہ میں اُحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اللہ کے نزدیک ان صحابہ کرام کے اس ایک مُد یا آدھے مُد کے برابر نہیں کہ جو انہوں نے ابتدائے اسلام میں راہِ خدا میں خرچ کیا تو پھر بعد کے عام مسلمان صحابہ کرام کے مثل کیسے ہوسکتے ہیں؟ اور یہ مقدس صحابہ کرام فقہ و فتاویٰ میں صواب و درستگی سے کیسے محروم کیے جا سکتے ہیں؟
۲۔ وعدن عبد اللہ بن مغفال المزنی قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوھم غرضا بعدی، فمن احبھم فبحبی احبھم، ومن ابغضھم فببغضی ابغضھم، ومن آذاھم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی اللہ، ومن آذی اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ [23]
ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مغفل سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے صحابہ کے سلسلہ میں اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو! میرے بعد انہیں نشانۂ تنقید و تنقیص نہ بناؤ کیونکہ جس نے اُن سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے اُن سے محبت کی اور جس نے اُن سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے اُن سے بغض رکھا اور جس نے انہیں ستایا اُس نے مجھے ستایا اور جس نے مجھے ستایا اُس نے اللہ کو ایذا پہنچائی اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو بہت جلد اللہ اُس کی گرفت فرمائے گا۔
خلاصہ یہ ہے کہ صحابۂ کرام کی عداوت اللہ و رسول سے عداوت و دشمنی اور بغض و کینہ رکھنے کی علامت ہے۔
۳۔ عن ابی بُردہ عَن ابیہ قال: رفع یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ الی السماء وکان کثیرا مما یرفع رأسہ الی السماء، قال النجوم امنہ لاھل السماء، فاذا ذھبت النجوم اتی اھل السماء مایو عدون وانا امنۃ لا صحابی، فاذا ذھبت اتی اصحابی مایوعدون، واصحابی امنۃ لا متی فاذا ذھب اصحابی اتی امتی مایوعدون۔ [24]
ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت ابو بُردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سرِ مبارک آسمان کی طرف اُٹھایا اور آقا اکثر اپنا سرِ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ اُس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا کہ تارے آسمان کے لیے امان ہیں لہٰذا جب تارے جاتے رہیں گے تو آسمان والوں کو وہ پہنچے گا جس کا اُن سے وعدہ ہے اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں تو جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ گزرے گا جس کا اُن سے وعدہ ہے اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں جب میرے صحابہ چلے جائیں تو میری اُمت کو وہ پہنچے گا جن کا اُن سے وعدہ ہے۔
واضح رہے کہ قیامت میں پہلے تار سے جھڑیں گے پھر آسمان پھٹیں گے اس لیے جب تک آسمان پر تارے ہیں تو آسمان محفوظ ہیں اسی طرح جب تک آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری حیات میں صحابہ کے درمیان موجود رہے صحابہ کرام آپسی لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہے۔ اسی طرح جب تک صحابہ کرام موجود رہے تب تک فتنے اتنے عام نہ ہوئے مگر جیسے ہی دورِ صحابہ ختم ہوا دین میں بگاڑ و فساد اور فتنے بے انتہاء پیدا ہوگئے۔
۴۔ عن عمران بن حصین قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی القرن الذی بعثت فیھم، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم۔ [25]
ترجمہ: حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اُمت میں سب سے بہترین جماعت وہ ہے کہ جس میں میں مبعوث ہوا۔ پھر وہ لوگ جو اُس سے قریب ہوں پھر وہ جو اُن سے قریب ہوں۔
اس حدیث پاک میں پہلے قرن سے مراد صحابہ کرام، دوسرے سے تابعین تیسرے سے تبع تابعین۔ زمانۂ صحابہ ظہور نبوت سے ۱۲۰؍ سال تک رہا یعنی ۱۰۰؍ ہجری تک، زمانۂ تابعین ۱۰۰؍ سے ۱۷۰؍ ہجری تک اور زمانۂ تبع تابعین ۱۷۰؍ ہجری سے ۲۲۰؍ ہجری تک۔ [26]
اس حدیث پاک سے تمام صحابہ کرام کا عادل، مظفر، منصور اور اخیار ہونا ثابت ہے۔
عدالت صحابہ اقوال ائمہ کی روشنی میں:۔
امام نووی فرماتے ہیں کہ الصحابۃ کلھم عدول یعنی تمام صحابہ عادل و ثقہ ہیں۔
· امام الحرمین فرماتے ہیں کہ اُن کی عدالت کے سلسلہ میں تحقیق و تفتیش نہ کیے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام شریعت کے علمبردار ہیں لہٰذا اگر ان کی روایت میں تفتیش عدالت کی بنیاد پر توقف ہوجائے تو شریعت مطہرہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے ہی تک محدود ہوجائے گی۔
· حضرت ابو ذرعہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو کسی صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ وہ بلا شبہ زندیق ہے کیونکہ ہمارے رسول حق، قرآن حق اور جو کچھ آقا لے کر آئے وہ حق اور یہ تمام چیزیں ہمیں صحابہ کرام ہی نے عطا فرمائیں۔ یہ زندیق چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو مجروح قرار دے کر قرآن و حدیث کے نصوص کو ہی مجروح کر ڈالیں۔
· امام ابن صلاح کا قول ہے تمام صحابہ کرام کی عدالت پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اب رہ گیا معاملہ حضرت علی اور حضرت معاویہ جیسے چند صحابہ کے درمیان ہونے والے مشاجرات کا تو اِن کا ثبوت علم تاریخ وغیرہ سے ہے جو صرف ظن کا افادہ کرتے ہیں لہٰذا ثبوت ظنّی، ثبوت قطعی کی تردید نہیں کرسکتا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے اُس کافیٔ مسلم میں کوئی حق نہیں۔
تفضیل صحابہ اور عقیدۂ اہل سنت:۔
یوں تو صحابہ کرام کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ [27]
اسی کے ساتھ ماقبل میں یہ بات بھی ثابت ہوچکی ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل و ثقہ ہیں۔ مگر اب سوال اس بات کا ہے کہ ان صحابہ کرام میں سب سے افضل صحابی کون سے ہیں؟ تو اس سلسلہ میں ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد مطلقاً سب سے افضل صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اُن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اِن دونوں کی افضیلت پر اہل سنت کا اجماع قائم ہے۔ اس اجماع کو نقل کرنے والے ابو العباس قرطبی فرماتے ہیں کہ ائمہ سلف و خلف میں سے کسی کا اس سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں اور اہل تشیع اور اہل بدعت کے اقوال کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت امام شافعی نے بھی صحابہ کرام اور تابعین حضرات کا تفضیل شیخین پر اجماع نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے افضل ہونے کے سلسلہ میں صحابہ کرام اور تابعین میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں البتہ حضرت علی اور حضرت عثمان میں سے کس کو کس پر افضیلت حاصل ہے اِس میں ضرور بعض لوگوں کا اختلاف ہے۔ مگر زیادہ تر اہل سنت کا رجحان اس طرف ہے کہ خلفائے راشدین میں افضیلت کا اعتبار اُن کی خلافت کے اعتبار سے ہے۔ یعنی سب سے پہلے حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔
حضرت ابو بکر کی افضیلت کے سلسلہ میں حضرت امام بخاری نے حضرت عمر و بن عاص کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اِن کے والد محترم! یعنی حضرتِ ابو بکر اسی طرح حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بخاری شریف میں ایک روایت اس طرح درج ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے برابر کسی کو نہ گردانتے، اُن کے بعد حضرت عمر کے برابر اور اُن کے بعد حضرت عثمان کے برابر کسی کو نہ سمجھتے تھے۔
محمد بن حنفیہ کی روایت میں یہ ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے حضرت ابو بکر کا نام لیا۔ میں نے کہا کہ اُن کے بعد تو اُنہوں نے حضرت عمر کا نام لیا۔ میں نے کہا کہ اُن کے بعد تو اُنہوں نے حضرت عمر کا نام لیا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں حضرت عمر کے بعد وہ حضرت عثمان کا نام نہ لے لیں اس لیے میں نے جلدی سے کہا کہ عمر کے بعد آپ؟ تو حضرت علی نے فرمایا میں تو مسلمانوں کا صرف ایک فرد ہوں۔ ان روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔
صحابہ کرام اور فقہ اسلامی:
قرآن کریم مجمل ہے جس کی توضیح حدیث نے فرمائی اور حدیث مجمل ہے جس کی تشریح شرعی اصولوں اور صحابہ کرام کے اقوال، افعال، اور احکام کی روشنی میں مجتہدین کرام نے فرمائی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اس ترتیب کو یوں بیان فرمایا گیا کہ ’’ تبیانا لکل شئی‘‘ یعنی قرآن کریم میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن میں نہ ہو مگر ساتھ ہی فرمادیا ’’وما یعقلھا الا العٰلمون‘‘ یعنی اس کی سمجھ نہیں مگر عالموں کو۔ اسی لیے قرآن کریم کے مجملات اور اس کے نصوص کے محمل و مراد کو جاننے اور سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا علم رکھنے والے نفوس قدسیہ کی بارگاہوں میں زانوئے ادب تہ کرنے کا یوں حکم دیا کہ ’’فاسئلوا اھل الذکر ان کنتم لا تعلمون‘‘
ترجمہ: علم والوں سے پوچھو اگر تم نہ جانتے ہو۔ چونکہ علم والے محض اپنے علم اور اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنے پر قادر نہیں بلکہ اس کے لیے انہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہونا ہوگا چانچہ اسی آیت سے متصل اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ:
’’وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس مانزل الیھم‘‘
ترجمہ: اے نبی ہم نے یہ قرآن تیری طرف اس لیے اتارا کہ تو لوگوں سے شرح بیان فرمادے اس چیز کی جو ان کی طرف اتاری گئی۔
چاروں آیات کا ترتیب وار اب حکم یہ رہا کہ اے جاہلو! تم علما کے کلام کی طرف رجوع کرو اور اے عالمو! ہمارے رسول کا کلام دیکھو تو ہمارا کلام سمجھ میں آئے۔ [28]
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس ظاہری دنیا میں موجود رہے تب تک صحابہ کرام کو اپنے تمام ترمسائل دینیہ اور مسائل دینویہ میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علاوہ کسی کی حاجت اور ضرورت نہ تھی۔ جب بھی انہیں کوئی ضرورت پیش آتی، یا قرآن کریم کی آیات کا محمل اور ان کی مراد سمجھنے کی ضرورت پڑتی یا کوئی نیا مسئلہ ان کے سامنے آتا اس کے سلسلہ میں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے تب آقا یا تو وحی کے ذریعہ یا اپنے اجتہاد کے ذریعہ انہیں ان کا مطلوبہ جواب عنایت فرما دیتے۔ اسی طرح کبھی یوں بھی ہوتا کہ ہر صحابی آقا سے پوچھنے کی ہمت نہ کر پاتے یا یہ کہ انہیں براہ راست معلوم کرنے کا موقع میسر نہ آتا تو وہ دوسرے صحابہ سے اس مسئلہ کا حکم دریافت کر لیتے تو یہ صحابہ کرام اپنے اجتہاد کے ذریعہ اس کا جواب عنایت فرما دیتے۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ صحابہ کرام کسی حکم عمومی کی توجیہ اپنے اجتہاد سے کر کے اس سےمسائل کا استخراج اپنے طور پر کرتے جس کی وجہ سے کبھی کبھی ایک فریق کا موقف دوسرے فریق کے خلاف ہوتا پھر آقا تک یہ معاملات پہنچتے تو جو فریق اپنے اجتہاد میں صواب پر ہوتا اس کو برقرار رکھتے اور تصویب فرما دیتے اور جس سے خطائے اجتہادی سرزد ہوجاتی اس کی خطائے اجتہادی کو واضح فرما دیتے مگر ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ خطائے اجتہادی کرنے والے صحابہ کرام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہو یا ان کی اتباع میں اس پر عمل کرنے والے لوگوں سے توبہ کا مطالبہ کیا ہو کیونکہ یہ خطا، خطائے عنادی نہیں بلکہ خطائے اجتہادی، وہ بھی خطائے مقرر کہ جس کے صاحب پر انکار نہیں کیا جاتا۔ اس لیے کہ یہ وہ خطائے اجتہادی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوتا جیسے احناف کے نزدیک مقتدی کا امام کے پیچھے سورۂ فاتحہ پڑھنا۔ [29]
بلکہ اس خطا پر تو مجتہد کو اجر دیا جاتا ہے۔ نیز اصول شرع اگرچہ چار ہیں کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ، اجماع اور قیاس مگر اصولی حضرات نے صحابہ کرام کے ان اقوال کو کہ جن کا حکم معقولی نہ ہو انہیں اجماع میں اور جن کا حکم معقولی ہو اُن کو قیاس میں داخل فرمایا ہے لہٰذا اقوال صحابہ بھی اصول شرع کا ہی حصہ ہیں۔ [30]
یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ تمام صحابہ کرام علم و فقہ میں برابر نہیں تھے۔ اس لیے غیر مجتہد صحابہ مجتہد صحابہ کرام کے احکام پر عمل پیرا ہوتے۔
یہ تو ان صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ جو مدینہ میں زندگی بسر فرماتے تھے۔ مگر وہ مسلمان جو ممالک مفتوحہ اور دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے تو وہ اپنے مسائل کا حل ان صحابہ کرام سے دریافت کرتے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ان دور دراز کے علاقوں میں وفد کی صورت میں بھیجے جاتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ تک شریعت اسلامیہ کے مسائل کا حل مذکورہ بالا طریقوں پر ہوتا رہا لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو سلطنت تشریعیہ خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ کرام کی طرف منتقل ہوگئی۔ جیسے جیسے سلطنت اسلامیہ اور فتوحات اسلامیہ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا ویسے ویسے مسائل جدیدہ بھی سامنے آتے رہے۔ ان ممالک مفتوحہ میں چونکہ صحابہ کی مقدس جماعت کثیر تعداد میں پھیل چکی تھی اس لیے جو بھی مسائل درپیش ہوتے تو مقامی سطح پر جو بھی صحابہ کرام وہاں ہوتے وہ ان مسائل کا حکم اور فیصلہ کتاب اللہ اور احادیث رسول کی روشنی میں جاری فرما دیتے۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا کہ جس کا حکم واضح طور پر وہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ میں نہیں پاتے تو اس کا جواب اپنے اجتہاد اور اپنی رائے کے ذریعہ پیش فرما دیتے کیونکہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ میں عدم وجدان کی صورت میں انہیں اسی کا حکم تھا جیسا کہ حدیث معاذ بن جبل میں اس کی تصریح ہے۔ سارے مسلمان ان فیصلوں پر عمل کرتے کیونکہ وہ تمام صحابہ کو عادل، ثقہ اور اپنے لیے مشعل راہ، اپنا ھاوی و رہنما، دین کی حجتیں اور ہدایت و رہنمائی کے ستارے جانتے۔ قرآن و حدیث اور اجماع امت کے مقضیات کی روشنی میں ان کی اقتداء کو اپنے لیے لازم اور باعث اہتداء جانتے۔ نیز ان کے بتائے ہوئے احکام پر نہ صرف یہ کہ وہ خود عمل کرتے بلکہ ان احکام کو امت مسئلہ کے ہر فرد تک پہنچانے میں اور ان کی ترسیل و تبلیغ میں دل و جان سے کوشاں رہتے۔ انہیں محفوظ رکھتے، ان کو ذخیرہ کرتے۔ ان کی جمع و تدوین کا اہتمام کرتے۔ اگر کسی کو ان کے حوالے سے پہنچے کسی مسئلہ میں تردد ہوتا تو وہ اپنے ذہنی خلجان کو دور کرنے کے لیے دور دراز کا سفرتہ کرتے حجاز مقدس، کوفا، بصرا، شام، مصرا، شام، مصر وغیرہ ان جگہوں پر آتا کہ جہاں متعلقہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت اقامت پذیر ہوتی۔ وہ دریافت کرتا اور یہ اس کی تصدیق و توصیح کر دیتے۔ اس طرح فقہ اسلامی کی ترتیب و تدوین ہوتی رہی اور مسائل فقہیہ کی جمع و تدوین کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسائل شرعیہ دینیہ کی جمع و تدوین اور اس کا یہ ذخیرہ صحابہ کرام کی اقتدا اور ان کے اقوال، افعال اور احکام پر عمل کرنے اور انہیں عادل، وثقہ ماننے جاننے اور تسلیم کرنے ہی پر مبنی ہے۔
ماقبل میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ بے شمار صحابہ کرام حجاز مقدس سے نکل کر ممالک مفتوحہ میں پھیل گئے تھے۔ جن میں سے کچھ ممالک محروسہ کے انتظامات میں مصروف رہتے، کچھ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے، کچھ اسلامی لشکر میں شامل ہوکر جہاد کے فرائض انجام دیتے اور کچھ حضرات علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے زندگی کو قف کر کے علوم دینیہ کے تشنگان کو سیراب کرتے جس کا حکم خود قرآن میں موجود ہے کہ ’’فلولا نفرمن کل فرفۃ منھم طائفۃ لیتفقھوا فی الدین‘‘۔ یہ حضرات ان شہروں کے حاکموں کے مشیر بھی ہوتے اور معلم بھی، مفتی بھی ہوتے اور قاضی بھی۔ چانچہ کوفہ میں حضرت عبد اللہ ابن مسعود، مصر میں عبد اللہ بن عمر و بن عاص، بصرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت انس بن مالک، شام میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت ابو درداء مستقل طور پر قیام پذیر ہوگئے۔ ان شہروں اور ان کے مضافات کے علاقوں میں زندگی بسر کرنے والے مسلمان اپنے دینی و شرعی مسائل میں ان کابر صحابہ کی طرف رجوع کرتے اور اپنے مسائل شرعیہ کا حل حاصل کرتے۔ اس کے ساتھ ہی یہ اکابر صحابہ کرام ان علاقوں میں اپنی علمی محفلیں اور درسگاہیں بھی سجاتے جن میں دینی علوم و معارف کے شائق و شیدا حضرات ان سے استفادہ کرتے، ان کی شاگردی اختیار کرتے اور علوم دینیہ یعنی قرآن و حدیث کی افہام و تفہیم میں درک و مہارت حاصل کرتے۔ مگر بہت سے صحابہ کرام حجاز مقدس ہی تشریف فر ما رہے جیسے مکۃ المکرّمہ میں حضرت عبد اللہ ابن عباس، مدینہ طیبہ میں حضرت زید ابن ثابت اور حضرت عبد اللہ ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) مکۃ المکرّمہ اور مدینہ طیبہ کے رہنے والے حضرات خصوصاً اور دیگر ممالک اور علاقوں کے ضرورت مند اور علوم دینیہ کی تحصیل کے شائق حضرات حجاز مقدس میں زندگی بسر کرنے والے ان اکابر صحابہ کرام کی طرف رجوع کرتے اور ان سے استفادہ کرتے۔ [31]
جیسے جیسے مسلمانوں کی ضرورتوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا ویسے ویسے ان صحابہ کرام کے افادہ و استفادہ کی ان علمی محفلوں اور درسگاہوں کی اہمیت و افادیت بھی بڑھتی چلی گئی۔ دور دراز سے بے شمار مسلمان ان موارد و مناہل اور علوم اسلامیہ کےان سر چشموں پر آکر اپنی علمی پیاس بھجاتے، شب و روز ان اکابر صحابہ کرام کی خدمت میں رہ کر علوم دینیہ کے موتی چنتے۔ ہر وقت قال اللہ وقال الرسول کے جانفزا نغمات شیریں سے علم و عمل کے یہ شائق اپنے وجود کو مسرور و مسحور کرتے۔ اس طرح ابتدائے اسلام میں علوم دینیہ و فقہیہ کے دو بڑے مراکز وجود میں آئے جنہیں تاریخ اسلام میں ’’مدرسۃ المدینہ ؍ مدرسۃ الحجاز‘‘ اور ’’مدرسۃ الکوفہ ؍ مدرسۃ العراق‘‘ کے نام سے جانا گیا۔
مدرسۃ المدینہ:
چونکہ حجاز مقدس نزول وحی کا مہبط و علاقہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مکۃ المکرّمہ پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور مدینۂ منورہ آپ کی جائے ہجرت ہونے کے ساتھ آخری آرامگاہ بھی ہے۔ نیز حجاز مقدس اکابر صحابہ کرام کا وطن اصل بھی ہے جہاں آقا نےاپنے صحابہ کرام کے ساتھ زندگی بسر فرمائی۔ اسی مقدس خطے سےاسلام کا سورج نمودار ہوا اور یہیں سے اسلام کا پیغام پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ اس کی اسی اہمیت اور عظمت کے پیش نظر پوری دنیا کے مسلمان ان دونوں شہروں سے جس قدس و محبت و عقیدت رکھتے ہیں اتنی کسی اورشہر سے نہیں رکھتے ان دونوں شہروں سے محبت اور عقیدت رکھنے کو وہ ایمان ہی کا حصہ لازمہ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے مکۃ المکرّمہ اور مدینہ طیبہ اسلام کے اولین اور اصلی مراکز، تبلیغ اسلامی کا منبع اور علوم اسلامیہ کا سر چشمہ بنے۔ اکابر صحابہ کی موجودگی میں مدرسۃ المدینہ کے بانی کی حیثیت سے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعارف ہوئے۔ ان کے بعد مدرسۃ المدینہ یا مدرسۃ الحجاز کے سربراہ حضرت سعید بن مسیّب بنے جو اس وقت اہل حرمین کے درمیان ایک ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ اس مرکز کی اہم شخصیات میں سات حضرات کو شمار کیا گیا۔ جنہیں تاریخ اسلام ’’فقہائےسبعہ بالمدینہ‘‘ کے نام سے جانتی ہے۔ ان سب کا سلسلۂ تلمذ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ان ساتوں حضرات کے اسماء یہ ہیں۔
ا۔ حضرت سعید بن مسیّب۔ ۲۔ حضرت عروہ بن زبیر۔ ۳۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق۔ ۴۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن حارث بن ہشام۔ ۵۔ حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود۔ ۶۔ حضرت سلیمان بن یسار۔ ۷۔ حضرت خارجہ بن زید بن ثابت۔
مدرسۃ الکوفہ ؍ مدرسۃ العراق:
پہلی صدی ہجری کے نصف میں عراق کے اندر علوم دینیہ فقہیہ کا ایک اور اہم مرکز اور ایک اور اہم سرچشمہ قائم ہوا جس کی بنیاد کوفہ میں پڑی۔ اس مرکز کے بانی کی حیثیت سے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعارف ہوئے۔ ان کی علمی محفل میں بے شمار علاقائی مسلمانوں کے علاوہ دور دراز کے خطوں اور ممالک محروسہ میں زندگی بسر کرنے والے اہل ایمان اپنے مسائل کا حل دریافت کرتے۔ بے شمار طالبان علوم دینیہ رات و دن ان کی خدمت میں رہ کر استفادہ کرتے، ان کے خوان علم و فضل سے علوم و معرفت اور حکمت و روحانیت کے درخشاں و تاباں جواہر چنتے۔
حضرت عبد اللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کرنے والے حضرات کی تعداد چھ ہے۔ جنہیں ’’فقہائے ستہ بالکوفہ‘‘ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں:
۱۔ حضرت علقمہ بن قیس نخعی۔ ۲۔ حضرت اسود بن یزید نخعی۔ ۳۔ حضرت مسعود بن یزدہ ہمدانی۔ ۴۔ حضرت عبیدہ بن عمر و سلمانی۔ ۵۔ حضرت شریح بن حارث قاضی۔ ۶۔ حضرت حارث اعور۔ [32]
فقہ حنفی کا سر چشمہ یہی مدرسۃ الکوفہ ہے۔ مسائل فقہ حنفی کے زیادہ تر مسائل کی مستدل احادیث کریمہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی مرویات میں سے ہیں۔ اس کے برخلاف فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی کے زیادہ تر مسائل کا منبع مدرستہ المدینہ ہے۔ نیز امام شافعی اکثر مسائل میں حضرت عبد اللہ ابن عباس کے تابع ہیں جس طرح حضرت امام اعظم اکثر مسائل میں حضرت ابن مسعود کے تابع۔
یہ بات معلوم ہوچکی ہے کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں دو طرح کے حضرات تھے۔ ۱۔ مجتہد صحابہ کرام۔ ۲۔ غیر مجتہد صحابہ کرام۔ لیکن یہ تقسیم تو روز بروز درپیش آنے والے ان مسائل جدیدہ کے اعتبار سے ہے کہ جن کا واضح حکم قرآن و حدیث میں نہیں ہوتا تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست علوم اسلامیہ کی تحصیل کی، رات و دن سفر و حضر میں آقا کی خدمت میں رہ کر تفقہ اور علم تشریعی حاصل فرمایا، کاروان حیات کے ہنگاموں سے دور رہ کر ’’اب تو غنی کے در پہ بستر جمادئیے ہیں‘‘ کا مظہر تاباں بن کر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہونے والے علوم و حکمت کے موتیوں سے اپنے دامنوں کو پُر کرنے میں لگے رہتے۔ آقا کے ہر قول و فعل اور تقریر کو محفوظ کرتے، آقا نے کسے کیا حکم دیا، کس کے فعل کو برقرار رکھا، کس کے قول و فعل پر نکیر فرمائی، کس موقع اور کن حالات میں کن لوگوں کو کیا حکم دیا؟ کیسے اٹھتے، کس طرح بیٹھتے، کس طرح چلتے، کس انداز میں سوتے، کیا پسند فرماتے اور کیا نا پسند فرماتے، کیسے وضو فرماتے، کیسے نماز ادا فرماتے، کیا کھاتے؟ اور کیا پیتے، کیا پہنتے اور کیا اوڑھتے، کس طرح خرید و فروخت کرتے، عبادات، معاملات، اور حدود و قصاص کے باب میں کیا کہا، کیا کیا اور کیا برقرار رکھا۔ غرض کہ آقا کی ہر ادا کو یہ اپنے قلب و ذہن کی تختی پر محفوظ بھی رکھتے اور ان کی تبلیغ و ترسیل بھی کرتے۔ انہیں سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر صحابہ کرام کی یہ مقدس جماعت روز بروز در پیش آنے والے نت نئے مسائل اجتہادیہ میں اپنے اجتہاد کے ذریعہ فیصلہ صادر فرماتی اور اسی کے مطابق حکم شرع بیان فرما دیتی۔ اب رہ گئے وہ صحابہ کرام جو درجۂ جتہاد پر فائز نہ تھے یہ حضرات ان ہی مجتہد صحابہ کرام کی اتباع کرتے۔ ان مسائل اجتہادیہ میں مذکورہ خصوصیات کےحامل صحابہ کرام کے ذریعہ جاری کردہ احکام پر خود بھی عمل کرتے اور دوسروں کو بھی ان پر عمل کرنے کی تلقین کرتے۔ ان احکام کو دوسروں تک پہنچانے کی سعی و کوشش کرتے اور ضرورت کے وقت مجتہد صحابہ کرام کے ذریعہ جاری کردہ احکام سے اشتہاد بھی کرتے۔
ان ساری تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام مسائل منصوصہ و واضحہ میں صحابہ کرام کے اقوال و افعال قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوتے اور مسائل اجتہاد یہ میں غیر مجتہد صحابہ کے اقوال و افعال مجتہد صحابہ کے اقوال، افعال اور احکام کے مطابق ہوتے۔ اسی لیے دور صحابہ کے بعد والے لوگوں کو قرآن و حدیث کی تفہیم، قرآن و حدیث سے مسائل شرعیہ کے استخراج او ران مصادر سے احکام شرعیہ کے استنباط و استدلال میں صحابہ کرام کے اقوال و افعال کی ضرورت پیش آئی۔ خواہ وہ اقوال و افعال مجتہد صحابہ کرام کے ہوں یا غیر مجتہد صحابہ کرام کے۔ نیز مجتہد صحابہ کرام کے یہ اقوال، افعال اور احکام اگرچہ صورتا ان کی طرف منسوب ہیں مگر در حقیقت ان کا موردو سر چشمہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور احکام، مجتہد صحابہ کرام کے اقوال، افعال اور احکام ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین نے فقہ اسلامی کی ترتیب و تدوین میں اپنے اجتہاد کے ذریعہ جن مسائل کا بھی استنباط کیا انہیں قرآن حدیث اور آثار صحابہ کے مطابق مانا گیا۔ استنباط مسائل میں ان مجتہدین کرام نے قرآن و حدیث کی تفسیر، تشریح، توضیح اور ان کی مراد کی تعیین میں صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں سے جس کسی صحابی رسول کےقول و فعل پر اعتماد و استناد کیا اور اس سلسلہ میں جس صحابی رسول کا بھی دامن تھام کر ان کی اقتدا و پیروی کی تو وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اسی مفہوم کا پتہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ملتا ہے کہ ’’عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی فأوحی الی یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضھا اقوی من بعض ولک نور فمن اخذ بشئی مماھم علیہ من اختلافھم فھو عندی علیٰ ھدی‘‘
ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق سوال کیا جو میرے بعد ہوگا تو مجھے وحی فرمائی گئی کہ اے محمد تمہارے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں کہ ان کے بعض بعض سے قوی ہیں اور سب میں نور ہے تو جس نے ان کے اختلاف میں سے کچھ حصہ لیا کہ جس پر وہ ہیں تو وہ میرے نزدیک ہدایت پرہے۔ واضح رہے کہ یہاں اختلاف سے مراد اجتہادی، علمی، علمی یعنی فقہی و شرعی مسائل میں اختلاف ہے۔ جو شخص کسی بھی صحابی کے فتوے پر عمل کرے گا نجات پا جائے گا۔ لہٰذا ائمہ مجتہدین جیسے حضرت امام اعظم اور امام شافعی وغیرہم صحابہ ہی کےمقلد ہیں۔ [33]
اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ظاہر اور اجماع کی رو سے تمام صحابہ مطلقاً عادل و ثقہ ہیں جیسا کہ ملا علی قاری نے فرمایا کہ ’’والصحابۃ کللھم عدول مطلقاً لظو اھر الکتاب والسنۃ واجماع من یعتد بہ‘‘ [34]
نیزان مجتہدین کے بیان کردہ مسائل پر ان کے مقلدین نےجو عمل کیا انہوں نے حق ہی پر عمل کیا اور وہ قرآن و حدیث ہی پر عمل کرنے والے کہلائے۔
حدیث اصحابی کالنجوم:۔
علوم اسلامیہ اور مسائل دینیہ و شرعیہ میں صحابہ کرام کی اسی اہمیت، افادیت، حیثیت اور اُن کی اسی امانت داری کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اقتدا و پیروی کرنے، ان کو بھلائی کے ساتھ یاد کرنے، ان کی شخصیات دینیہ کو ھادی و رہنمائی مانئے، ان سب کو عادل و ثقہ تسلیم کرنے، ان کی ذوات مقدسہ کو نشانہ تنقید بنا کر اُن کی حیثیت دینیہ کو مجروح نہ کرنے، اُن کو سب و شتم نہ کرنے، انہیں برانہ کہنے اور انہیں دین کی حجتیں ماننے کا حکم ایسی بہت سی حدیثوں کے ذریعہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاری فرمایا جو قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہے۔ ان میں سے بہت حدیثیں وہ ہیں کہ جو محدثین کے معیار و منہج پر درجۂ صحت تک پہنچی ہوئی ہیں۔ مگر کچھ وہ ہیں کہ جو ان محدثین کی کسوٹی کے مطابق اصطلاحاً درجۂ صحت تک تو نہیں پہنچتی کہ اُن کی سندوں میں ضعف اور ان کے راوی متکلم فیہ ہیں۔ مگر انہیں ہر دور کے علمائے ملت اسلامیہ کا قبول عام حاصل رہا ہے، ان کے درمیان وہ حدیثیں مشہور بھی رہی ہیں اور اُن کی نقل و کتابت بھی ہوتی رہی ہے۔ اہل علم نے اُن پر عمل بھی کیا ہے اور اُن سے استناد بھی، بلکہ انہوں نے ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں نقل کرنے کے بعد مسائل کا استخراج بھی فرمایا ہے۔
صحابہ کرام کی اقتدا و اتباع کا حکم دینے والی، انہیں امت کا ہادی و رہنما اور محافظ و پاسبان ماننے کی دعوت دینے والی اور بہت سی صحیح حدیثوں کے مذکورہ مفہوم سے یکسانیت و متابعت رکھنے والی ایک حدیث پاک یہ بھی ہے جس میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ’’اصحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم اھتدیتم‘‘ یعنی میرے تمام صحابہ ستاروں کے مثل ہیں تم ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔
حدیث اصحابی کالنجوم کی تخریج:۔
یہ حدیث پاک الفاظ کے اختلاف اور معانی کی یکسانیت کے ساتھ
۱۔ حضرت عمر۔ ۲۔ حضرت عبد اللہ عمر۔ ۳۔ حضرت جابر بن عبد اللہ۔ ۴۔ حضرت ابو ہریرہ۔ ۵۔ حضرت انس بن مالک۔ ۶۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے چھ مقدس صحابہ کرام سے مروی ہے۔ جسے مندرجہ ذیل کتابوں میں نقل کیا گیا ہے:
ابن عبد البر کی کتاب جامع بیان العلم، خطیب کی الکفایہ فی علم الروایہ بیہقی کی المدخل، دیلمی کی فردوس، دیلمی ہی کی مسند، ابن عسا کر کی تاریخ دمشق، ابن عدی کی کامل، آجری کی الشریعہ، عبد بن حمید کی مسند، ابن بطہ کی الابانہ، علامیہ ابن حجر کی موافقہ اور الامالی، قاضی عیاض کی الشفاء۔ [35]
ان کے علاوہ متقدمین و متاخرین کی اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔
حدیث اصحابی کالنجوم کی سندیں:
جیسا کہ مذکور ہوا کہ یہ حدیث پاک مندرجہ بالا کتابوں میں چھ صحابہ کرام کے حوالہ سے منقول ہے۔ جسے مذکورہ بالا ائمہ نے اپنی مختلف سندوں سے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ اب ہم ہر ایک صحابی کو مروی اس حدیث پاک کی سندوں پر اجمالی گفتگو کریں گے۔
حدیث عبد اللہ بن عمر کی سند:
حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی اس حدیث پاک کو عبد بن حمید نے اپنی مسند میں، انہیں کی سند سے علامہ ابن حجر نے ’’الامالی المطلقہ‘‘ اور ’’موافقۃ الخبر الخبر‘‘ میں احمد ابن یونس کے حوالہ سے اور ابن بطہ نے الابانہ الکبریٰ میں موسیٰ بن اسحاق انواری کے حوالہ سے یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ پھر آجوری نے شریعہ میں، ابن عدی نے کامل میں، ابو الفضل زہری نے اپنی کتاب ’’حدیثہ‘‘ میں ابن بطہ نے الابانۃ الکبریٰ میں عمر و بن عثمان کلابی ہے۔ پھر ابن یونس اور کلابی نے ابو شہاب الحناط سے اور ابن عدی نے کامل میں غسان بن عبید سے پھر ابو شہاب اور غسان بن عبید نے حمزہ بن ابی حمزہ الجزری النصیبی سے، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً یہ حدیث روایت کی۔ اس طرح عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کی مندرجہ ذیل سندیں ہوئیں۔
۱۔ عبد بن حمید نے احمد بن یونس سے انہوں نے ابو شہاب سے انہوں نے حمزہ ابن ابی حمزہ جزری نصیبی سے انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔
۲۔ آجری و ابن عدی و ابو الفضل الزہری و ابن بطہ نے عمر و بن عثمان کلابی سے انہوں نے ابو شباب سے انہوں نے حمزہ سے انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر سے۔
۳۔ ابن عدی نے کامل میں غسان بن عبید سے انہوں نے حمزہ سے انہوں نے نافع سے انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے۔
نوٹ:۔ ان سندوں میں سے عمر بن عثمان کلابی عن ابی شہاب والی روایت عن احمد یونس والی روایت سے عالی ہے۔
مذکورہ بالا سندوں سے مروی اس حدیث کا دار و مدار حمزہ بن ابی حمزہ جزری پر ہے جنہیں متروک الحدیث، متہم بالوضع کہا گیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے انہیں مطروح الحدیث، ابن معین نے ’’لیس یساوی فلساً‘‘ اور امام بخاری نے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ نافع سے اس حدیث کی روایت میں یہ تنہا ہیں جسے ان کی علاوہ کسی نے بھی نافع سے روایت نہیں کیا۔
حدیث جابر بن عبد اللہ کی سندیں:۔
حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث دو سندوں سے مروی ہے۔
۱۔ دار قطنی نے فضائل الصحابہ اور المؤتلف والمختلف میں اورانہیں کی سند سے ابن حزم نے احکام میں، ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ میں، ابن مندہ نے فوائد میں، ابن حجر نے امالی اور موافقہ میں ابو طاہر سلفی نے المشیخۃ البغدادیۃ میں سلام بن سلیمان سے، انہوں نے حارث بن غصین سے انہوں نے اعمش سے انہوں نے ابو سفیان سے انہوں نے جابر بن عبد اللہ سے یہ حدیث مرفوعاً روایت کی۔
اس سند کا مدار حارث بن غصین پر ہے۔
۲۔ دار قطنی نے غرائب مالک میں جمیل بن یزید سے انہوں نے مالک بن انس سے انہوں نے جعفر بن محمد سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعا یہ حدیث روایت کی۔
۱۔ اس حدیث کی پہلی سند کے راوی سلام بن سلیمان کی کچھ ائمہ نے تضعیف فرمائ ہے۔ اور ان کی کچھ احادیث میں منکر حدیثیں بتائی گئی ہیں۔ چنانچہ ابو حاکم نے انہیں ’’لیس بالقوی‘‘، عقیلی نے ’’فی حدیثہ عن الثقات مناکیر‘‘، ابن عدی نے ھو عندی منکر الحدیث بتایا ہے۔ ان کے شیخ حارث بن غصین کا ذکر امام بخاری نے تاریخ کبیر میں کیا مگر ان کے سلسلہ میں نہ کوئی جرح ذکر کی اور نہ ہی تعدیل، ابن حبان نے انہیں ثقات میں شمار کیا ہے۔ مگر ابن عبد البر اور علائی نے ان پر مطلقاً مجہول ہونے کا حکم لگایا ہے۔ البتہ زرکشی نے مجہول الحال کا مقید حکم لگایا۔ علائی نے کہا کہ میں نے ان کے ذکر میں نہ توثیق پائی نہ جرح۔ زرکشی نے کہا کہ میں نے ان کے ذکر میں سے کچھ نہیں جانتا۔ البتہ ابن حجر نے فرمایا کہ ابن حبان نے انہیں ثقات میں ذکر کیا ہے۔ ابن عبد البر نے سلام بن سلیمان کی مذکورہ سند سے مروی اس حدیث کی تضعیف فرمائی۔ چنانچہ ابن عبد البر نے کہا ’’ھذا اسناد لا تقوم بہ حجۃ الان الحارث بن غصین مجھول‘‘۔
یہ حدیث جتنی بھی سندوں سے مذکور ہوئی ان میں سب سے عالی سند یہی ہے۔ اب رہا ابن عبدالبر، ابن حزم اور علائی کا حارث پر مجہول ہونے کا طعن تو علامہ ابن حجر نے اسے یوں ردّ فرما دیا کہ عام ائمہ جرح و تعدیل سے ان کے سلسلہ میں جرح و طعن مذکور نہ ہوا۔ سوائے ان تینوں حضرات کے جب کہ اس کے برعکس ابن حبان نے انہیں ثقات میں شمار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان سے حسین بن علی جعفی نے روایت لی ہے لہٰذا اب ان سے روایت لینے والے حضرات کی تعداد دو ہوگئی۔ اب ان کی توثیق کی جائے گی اور انہیں مجہول نہ کہا جائے گا۔ [36]
حارث سے روایت لینے والے سلام بن سلیمان کہ جن پر عقیلی، ابن عدی، ابو حاکم اور ابن حزم نے کلام کیا ہے تو اس کے رد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام نسائی نے اپنے بعض مشائخ سے ان کی توثیق نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ صحیح سند سے مروی حضرت عبد اللہ ابن عباس کی اُس حدیث سے اس کا شاہد بھی موجود ہے۔ جس سے اس حدیث کے مفہوم و معنی کی تائید ہوتی ہے کہ جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا جس کے الفاظ یہ ہیں النجوم امان لاھل السماء والا صحابی امان لامۃ۔ پہلی حدیث میں صحابہ کو نجوم سے تشبیہ دی گئی اور دوسری میں نجوم و صحابہ کااطلاق یکساں طور پر کیا گیا جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ صحابہ کو نجوم سے تشبیہ دینا صحیح ہے۔ پھر چونکہ سمندری کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں اور سمندر کی ہولناک لہروں کے درمیان سمندری سفر میں ستاروں سے ہی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے زرّیں دور گزر جانے کے بعد جب دین میں نت نئے فتنے جنم لینے لگیں تو فتنوں، بدعتوں، بدعقیدگیوں سے بھر پور اور سنتوں کو مٹانے والے تیرہ و تاریک اس دور میں صحابہ کرام کے اقوال، افعال اور احکام سے روشنی، ہدایت اور رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ اھتداء یعنیی ہدایت حاصل کرنا یہ اقتداکی فروغ ہے کیونکہ بنا اقتدا کے یہ رہنمائی ممکن و متصور نہیں۔ [37]
لہٰذا مذکورہ تشریح کے مطابق حدیث اصحابی کالنجوم کے مفہوم کی تائید حدیث مسلم سے بجا طور پر ہو رہی ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ علامہ ابن حجر نے اگرچہ اولاً اس سند سے مروی اس حدیث کو ’’ضعیف واہ‘‘ یعنی یہ حدیث ضعیف واہی ہے کہا اور ساتھ ہی ابن حزم کا قول ’’موضوع باطل‘‘ نقل کیا مگر پھر استدراک کے طور پر امام بیہقی کا مذکورہ قول کہ حدیث سے اس کے معنی کی تائید ہوتی ہے، نقل فرما کر جہاں ابن حزم کے قول ’’موضوع باطل‘‘ کا صریح ردّ فرمایا وہیں اصحابی کالنجوم کی توثیق بھی فرما دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ سند سے مروی یہ حدیث ضعیف سے ترقی کر کے حسن کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔
۲۔ اس حدیث کی دوسری سند جو جمیل بن یزید عن مالک بن انس ہے اس کے سلسلہ میں کہا گیا کہ اس کی اسناد میں مجہول راوی ہیں۔ جن کی وجہ سے اس حدیث کی تضعیف کی جائے گی۔ دار قطنی نے اس کی تخریج کے بعد کہا کہ یہ مالک سے ثابت نہیں ہے اور اس کو مالک سے روایت کرنے والے راوی مجہول ہیں۔ ابن ملقن نے کہا: اس جمیل کو میں نہیں پہچانتا۔ حالانکہ مذکورہ طعن سے کوئی شدید حکم نہیں لگتا اور پھر یہ کہ ان کے راویوں سے الزام جہالت کو بھی رفع کر دیا گیا ہے۔
حدیث ابو ہریرہ کی سندیں:۔
اس حدیث کو قضاعی نے مسند شہاب میں جعفر بن عبد الواحد ہاشمی سے اور انہوں نے وہاب بن جریر بن حازم سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ اس حدیث کا دار و مدار جعفر بن عبد الواحد ہاشمی پر ہے اور وہ اسے اس سند سے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔ ابن حبان نے ان کے بارے میں کہا کہ ’’یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو حدیث سرقہ کرتے ہیں اور حدیثوں میں الٹ پھیر کر دیتے ہیں چنانچہ یہ حدیث کے اس متن صحیح کو جو اپنی کسی ایک سند سے مشہور ہے اسے دوسری سند سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ ان کی یہ کاریگری محسوس نہیں ہو پاتی اور یہ اپنی روایت میں ’’حدثنا‘‘ نہیں کہتے بلکہ ’’قال لنا فلاں بن فلاں‘‘ کہتے ہیں۔ ذہبی نے اس حدیث کو ذکر کر کے جعفر بن عبد الواحد کے حالات کے ضمن میں کہا کہ ’’یہ حدیث جعفر کی بلاؤں میں سے ہے‘‘۔ زیلعی نے جعفر بن عبد الواحد کی وجہ سے اس حدیث کو معلول قرار دیا۔ ابن حجر نے کہا کہ ’’اس کی اسناد میں جعفر بن عبد الواحد ہے اور وہ کذاب ہے‘‘۔ حالانکہ آگے اس بات کی وضاحت آرہی ہے کہ علامہ ابن حجر سے جعفر کی توثیق منقول ہے۔
حدیث عمر بن خطاب کی سندیں:۔
دارمی نے اس حدیث کو علل میں، ابن عدی نے کامل میں، ابن بطہ نے ابانہ میں، ابوذرحربی نے کتاب السنہ میں، بیہقی نے مدخل میں، خطیب بغدادی نے فقیہ اور کفایہ میں، نظام الملک نے امالی میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، ابن حجر نے موافقہ میں اور ابو طاہر سلفی نے مشیخہ میں، نعیم بن حماد سے انہوں نے عبد الرحیم بن زید عمی سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے سعید بن مسیّب سے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعا اس حدیث کا شاہد روایت کیا۔ اس حدیث کے راوی نعیم بن حماد کو حدیث کا امام کہا جاتا ہے۔ البتہ عبد الرحیم بن زید کے بارے میں ابن معین اور امام بخاری نے ’’ ترکوہ‘‘ اور ابو داؤد نے ’’لا یکتب حدیثہ‘‘ اور ابو حاکم نے ’’ترک حدیثہ‘‘ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں اضطراب کا بھی قول کیا گیا ہے۔ اس اضطراب کی وجہ ائمہ نے یہ ذکر کی ہے کہ عبد الرحیم کے والد زید عمی کبھی تو یہ حدیث سعید بن مسیّب عن عمر روایت کرتے ہیں اور کبھی عن سعید عن ابن عمر اور کبھی بغیر سعید بن مسیّب کے عن ابن عمر روایت کرتے ہیں اسی وجہ سے ابو بکر بن بزار نے کہا کہ یہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درجۂ صحت کو نہیں پہنچتا۔ آگے آئے گا کہ جب اس حدیث کا دار و مدار صرف عبد الرحیم پر نہیں اور پھر اس کا شاہد اور متابع بھی ہے تو اس سند پر وارد یہ کلام حدیث کی اصل ہونے پر اثر انداز نہ ہوگا۔
حدیث انس کی اسناد:۔
اس حدیث کو ابن ابی عمر نے اپنی مسند میں اور ابن حجر نے موافقہ میں سلام طویل سے انہوں نے زید عمی سے انہوں نے یزید رقاشی سے انہوں نے انس بن مالک سے مرفوعا ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ’’مثل اصحابی فی امتی مثل النجوم یھتدون بھا، اذا غابت تحیروا‘‘ یعنی میری امت میں میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے کہ جن سے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں مگر جب یہ چھپ جاتے ہیں تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اس حدیث کو سلام نے زید عمی کے حوالہ سے روایت کیا ہے۔ ان کے بارے میں ابن حجر نے فرمایا کہ اس کی اسناد میں تین ضعیف راوی ہیں۔ سلام، زید اور یزید۔ ان تینوں میں سب سے شدید ضعف سلام میں ہے۔ ابن حجر نے ان پر ’’واہ‘‘ کا حکم لگایا۔ بوصیری نے اس سند کو یزید رقاشی اور یزید عمی کی وجہ سے ضعیف قرار دیا۔
حدیث عبد اللہ ابن عباس کی اسناد:۔
یہ حدیث دو سندوں سے مروی ہے۔ ۱۔ ابو عباس اصم نے اپنی کتاب ’’حدیثہ‘‘ اور بیہقی نے انہیں کی سند سے مدخل میں، خطیب نے کفایہ میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، نصر بن ابراہیم نے تحریم میں، سلیمان بن ابی کریمہ سے نیز یحیی بن سلام نے ’’تفسیرہ‘‘ میں ابو ذرحربی نے کتاب السنہ میں، مندل بن علی کی سند سے، نیز بیہقی نے مدخل میں ابو ذرعہ کی سند سے، انہوں نے ابراہیم بن موسیٰ سے، انہوں نے یزید بن حارون سے روایت کیا۔ ابن ابی کریمہ، مندل اور یزید بن ھارون تینوں نے متفقہ طور پر جویبر سے روایت کیا۔ پھر اس سے اگلے راوی میں یہ تینوں مختلف ہوگئے۔ چنانچہ ابن ابی کریمہ نے جویبر سے انہوں نے ضحاک سے اور انہوں نے ابن عباس سے۔ اس کے برخلاف مندل نے جویبر سے اور جویبر نے ضحاک سے اور انہوں نے مرسلا رسول پاک سے۔ اس کے برعکس جویبر نے جواب بن عبید اللہ سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔
۲۔ ابن بطہ نے ابانہ میں موسیٰ بن اسحاق الانواری سے، انہوں نے احمد ابن یونس سے، انہوں نے ابو شہاب سے، انہوں نے اور ابن بطہ نے حمزہ سے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً یہ حدیث روایت کی ہے۔
اس حدیث کی پہلی سند کا دار و مدار جویبر پر ہے جن کے سلسلہ میں متروک الحدیث، متفق علی ضعفہ جیسے کلمات وارد ہوئے اس کے علاوہ اس کی بعض سندوں میں ارسال بھی ہے۔
خلاصہ:۔
حدیث پاک اصحابی کالنجوم کے سلسلہ میں مذکورہ بالا گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ائمہ نے اس کی سندوں پر ضعف کا حکم لگایا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل نے ’’لایصح ھذا الحدیث‘‘، امام بیہقی نے ’’ھذا حدیث متنہ مشھور و اسانیدہ ضعیفۃ لم یثبت فی ھذا الاسناد‘‘، علائی نے لم یخرج فی الکتب النسۃ ولا فی المسانید الکبار وقد روی من طرق فی کلھا مقال‘‘ ابن کثیر نے ’’لا یصح شی منھا‘‘ اور ابن ملقن نے ’’ھذا الحدیث غریب لم یروہ احد من اصحاب الکتب المعتمد ولہ طرق‘‘ جیسے تبصرے کر کے اس کی تضعیف فرمائی ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ائمہ کرام کے نزدیک یہ حدیث مذکورہ بالا سندوں کی وجہ سے ضعیف ہے۔
اگرچہ حدیث اصحابی کالنجوم مذکورہ بالا سندوں کے اعتبار سے ضعیف قرار دی گئی ہے مگر ان تمام سندوں کے ضعیف ہونے کے باوجود ائمہ نے شاہد کے طور پر اس کی مویٔد کچھ ایسی حدیثیں نقل فرمائی ہیں کہ جن سے اس حدیث کے معنی کی تائید بھی ہوتی ہے، متابعت بھی ہوتی ہے، اور ان احادیث صحیحہ سے اصحابی کالنجوم کے معنی و مفہوم کو تقویت بھی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی متابعت میں شاہد کے طور پر وہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ جس کی سند حسن مقبول ہے۔ اور جس سے اصحابی کالنجوم کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ حضرت قاضی عیاض خود ایک ناقد اور جرح و تعدیل کے اماموں میں سے ہیں جو راویان حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں لہٰذا ان کا کسی حدیث کو نقل کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ان کے پاس ضرور کوئی ایسی سند رہی ہے کہ جو ان کے نزدیک ثابت و بے غبار ہے۔ اسی وجہ سے قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے صیغۂ جزم کے ساتھ اس حسن مقبول حدیث سے متصلا ’’اصحابی کالنجوم‘‘ کو اپنی کتاب شفاء میں نقل فرمایا ہے کہ
حدثنا القاضی ابو علی، حدثنا ابو الحسین و ابو الفضل قالا حدثنا ابو یعلیٰ، حدثنا ابو علی السنجی، حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا الترمذی، حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا سفیان بن عیینہ عن زائدہ عن عبد الملک بن عمیر عن ربعی بن حراش عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، وقال اصحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم اھتدیتم (الشفاء، القسم الثانی فی مایجب اللانام من حقوقہ، الباب الثالث فی تعظیم امرہ، [38]
ترجمہ: ہم سے حدیث بیان کی قاضی ابو علی نے ان سے ابو الحسین اور ابو الفضل نے ان سے ابو یعلیٰ نے ان سے ابو علی نے ان سے محمد بن محبوب نے ان سے ترمذی نے ان سے حسن بن صباح نے ان سے سفیان بن عیینہ نے۔ وہ روایت کرتے ہیں زائدہ سے وہ عبد الملک بن عمیر سے وہ ربعی بن جراش سے اور وہ حضرت حذیفہ ابن یمانی سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا اور فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے تم جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔
اس حدیث کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ چنانچہ قاضی ابو علی کے بارے میں امام ذہبی نے فرمایا کہ ان کی حدیث متن و سند کے لحاظ سے حسن ہوتی ہے۔ اس کے دوسرے راوی ابو الحسین مبارک بن عبد الجبار کے سلسلہ میں علامہ ابن حجر اور امام ذہبی نے فرمایا کہ یہ ثقہ سند ہیں۔ اس کے تیسرے راوی ابو الفضل بن حسن بغدادی کو یحیٰ بن معین اور امام ذہبی نے ثقہ حافظ فرمایا۔ اس کے چوتھے راوی ابو یعلی بن احمد بغدادی کو خطیب بغدادی نے حدیث میں حسن بتایا۔ اس کے پانچویں راوی ابو علی السنجی کو خطیب بغدادی نے شیخ کبیر اور ثقہ بتایا۔ اس کے چھٹے راوی محمد بن محبوب یہ امام ترمذی کے شاگر ہیں جنہیں امام حاکم اور امام ذہبی نے ثقہ حافظ قرار دیا۔ اس کے ساتویں راوی حضرت امام ترمذی ہیں جن کے حفظ و ثقاہت میں کسی کو شک نہیں۔ اس کے آٹھویں راوی حسن بن صباح واسطی ہیں جنہیں امام احمد نے ثقہ، سنت کا پیروکار اور ابو حاکم و ابن حجر نے صدوق بتایا۔ اس کے نوے راوی سفیان بن عینیہ ہیں جو ائمہ حدیث میں ایک مشہور امام اور ثقہ ہیں۔ اس کے دسوے راوی زائدہ بن قدامہ ثقفی ہیں جنہیں ابو حاتم، امام نسائی اور امام حجر ثقہ بتاتے ہیں۔ گیارہ ہوے راوی عبد الملک بن عمیر ہیں امام ذہبی، ابو حاکم اور ابن حجر نے جن کی توثیق فرمائی ہے۔ اس کے بارہوے راوی ربعی بن جراش ہیں جنہیں ابن سعدی، ذہبی اور ابن حجر نے ثقہ بتایا ہے۔ یہ حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ نے روایت فرمائی جو صحابی رسول ہیں اور تمام صحابہ کرام عادل و ثقہ ہیں۔ ان میں سے کسی کی عدالت و ثقاہت پر شک کرنا ہی نقص ایمان کی علامت ہے۔ [39]
قاضی عیاض کی نقل کردہ اس حدیث کے تحت ملا علی قاری امام حلبی کے اس تبصرہ پر کہ قیاضی عیاض کو صیغۂ جزم کے ساتھ اسے نقل نہیں کرنا چاہیے تھا، اس پر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ قاضی عیاض کے نزدیک کسی صحیح سند سے یہ ثابت ہو یا اس اصول کے پیش نظر کہ کثرت طرق کی وجہ سے ضعیف حدیث حسن کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کے حسن ہونے پر اعتماد کیا ہو۔ نسیم الریاض میں علامہ خفاجی نے اس حدیث کے تحت فرمایا کہ فلو قال انہ بمعنی حدیث الذی قبلہ وھو حدیث صحیح یعمل بہ ولذا ساقہ بعدہ کالمتابعۃ لہ ولذا جزم بہ کان اقویٰ واحسن۔ یعنی صیغۂ جزم کے ساتھ نقل کرنے کی وجہ یہ بیان کی جائے کہ اصحابی کالنجوم اس حدیث کے ہم معنی ہے جس کو قاضی عیاض نے اس سے پہلے اتصال کے ساتھ نقل فرمایا اور چونکہ یہ حدیث، حدیث صحیح ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے اسی وجہ سے حضرت قاضی عیاض اصحابی کالنجوم کو اس حدیث صحیح کے بعد اس کے شاہد اور متابع کے طور پر لیکر آئے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جزم کے ساتھ اسے نقل فرمایا۔ [40]
متقدمین و متاخرین علمائے ملت اسلامیہ کے درمیان یہ حدیث پاک مشہور و مقبول رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کرام نے اس حدیث پر احکام اور فضائل میں اعتماد بھی کیا اور اس کی تصحیح بھی فرمائی۔ چنانچہ قاضی ابو یعلیٰ نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل اس سے احتجاج فرماتے تھے اور فضائل صحابہ میں اس پر اعتماد کرتے تھے۔ اسی طرح امام عثمان دارمی نے بھی اس پر اعتماد کیا ہے۔ فقہاء اور ائمہ اصول نے اس حدیث پاک سے اپنی کتابوں میں استشہاد کیا ہے۔
· امام سرخسی نے مبسوط کی ادب قاضی کے ضمن میں یہ بیان کیا ہے کہ قاضی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے جب کوئی مقدمہ پیش ہو تو سب سے پہلے وہ کتاب اللہ سے، اگر اس میں نہ پائے تو حدیث پاک سے اور اگر اس میں بھی اس کی نظر اس مقدمہ کا حل تلاش نہ کر پائے تو صحابہ کرام کے اقوال پر نظر کرے۔ لہٰذا صحابہ کرام میں سے کسی کا قول جب مل جائے تو اس کے مطابق فیصلہ کرے اور اسے قیاس پر مقدمہ کرے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ’’اصحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم اھتدیتم‘‘۔
· مسجی نے صحابی کی تقلید کی سلسلہ میں اپنی کتاب ’’اللباب‘‘ میں فرمایا کہ ہمارے بعض اصحاب کا یہ قول ہے کہ صحابی کی تقلید واجب ہے خواہ وہ قیاس کے موافق ہو یا مخالف۔ یہ قول ابو سعید برزعی اور ان کے متبعین کا ہے۔ انہوں نے اس مسئلہ میں دلیل بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ’’اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر‘‘ اور ’’اصحابی کالنجوم‘‘ کو۔
· امام نفراوی مالکی نے کہاکہ صاحب جوہرہ کا قول ہے کہ اسلاف میں سے صالحین کی اتباع کریں کیونکہ ہر مکلّف اس بات کا مامور ہے کہ وہ اپنےعقائد، اپنے اقوال، اپنے احوال اور اپنی حیات میں صالحین کی جماعت کا اتباع کرے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ’’علیکم بسنتی الخ‘‘ اور ’’اصحابی کالنجوم‘‘۔
· امام ماوردی شافعی نے الحاوی الکبیر میں فرمایا کہ بعض محدثین نے صحابہ کرام ہی کی تقلید کو جائز قرار دیا ہے، تابعین کی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اصحابی کالنجوم الخ کی وجہ سے۔
· ابن قدامہ حنبلی نے ایک مسئلہ کےسلسلہ میں مغنی میں اصحابی کالنجوم سے استناد کیا۔ [41]
· حضرت ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں اس حدیث پاک سے اسناد کرتے ہوئے فرمایا کہ ’’ولذلک ذھب جمھور العلماء الی أن الصحابۃ رضی اللہ عنھم عدول قبل فتنۃ عثمان وکذا بعدھا۔ ولقولہ علیہ الصلاۃ والسلام: أصحابی کالنجوم بأیتھم اقتدیتم اھتدیتم۔ ’’یعنی (اسی مذکورہ بالا حدیث کہ جب میرےصحابہ کا ذکر ہو تو رک جاؤ) کی وجہ سے جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں برپا ہونے والی بغاوت سے پہلے یا اس واقعہ کے بعد، بہر حال ہر دور میں تمام صحابہ عادل ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مثل ہیں کہ ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ [42]
حدیث ضعیف کی تقویت کے اسباب:۔
یہ بات مشہور و معروف ہے کہ حدیث ضعیف فضائل اعمال، مناقب، استحباب، احتیاط کے مقامات اور احکام کراہت میں مقبول و معتبر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں جن کی وجہ سے حدیث ضعیف میں تقویت پیدا ہوجاتی ہے حتیٰ کہ یہ احکام والی حدیث کی بھی ناسخ بن جاتی ہے۔ ان میں چند اسباب مندرجہ ذیل ہیں:
۱۔ تلقی بالقبول:۔
وہ حدیث ضعیف جسے امت کے متقدمین و متاخرین علما و ائمہ نے قبول کر لیا ہو تو ایسی حدیث تلقی بالقبول کہلاتی ہے۔ جس کے بعد وہ قابل عمل ہوجاتی ہے۔ علامہ سخاوی شرح الفیہ میں فرماتے ہیں کہ اذا تلقت الامت الضعیف بالقبول یعمل بہ الصحیح حتی انہ ینزل منزلۃ المتواتر فی انہ ینسخ المقطوع بہ والھذا قال الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فی حدیث ’’لا وصیۃ لوارث‘‘ انہ لا یثبت اھل العلم بالحدیث ولکن العامۃ تلقتہ بالقبول وعملوا بہ حتی جعلوہ ناسخا لایۃ الوصیۃ لوارث۔ یعنی علامہ سخاوی نے شرح الفیہ میں فرمایا کہ جب حدیث ضعیف کو امت قبول کر لے تو صحیح یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ یقینی اور قطعی حدیث کو منسوخ کرنے میں متواتر حدیث کے رتبہ میں سمجھی جائے گی اور اسی وجہ سے امام شافعی نے حدیث لا وصیۃ لوارث کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس حدیث کومحدثین ثابت نہیں کہتے لیکن ائمہ علماء نے اس کو قبول کر لیا اور اس پر عمل کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ حدیث وارث کے حق میں وصیت کا حکم دینے والی آیت۔ ’’کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیۃ للوالدین۔ الآیۃ‘‘ (مفہوم آیت:۔ تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آئے اور اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے)۔ کی ناسخ بن گئی۔
۲۔ تعامل:۔
کوئی حدیث سند کے اعتبار سے کتنی بھی مضبوط و قوی کیوں نہ ہو اگر امت کا عمل اُس پر نہیں ہے تو اس کی حجیت قطعی نہیں رہتی نسخ کے احتمال کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے محدثین کرام حدیث کی حجیت پر اس کے معمول بہ ہونے کابھی اعتبار کرتے ہیں چنانچہ وکیع نے اسمٰعیل بن ابراہیم مہاجر سے نقل کیا کہ حفظ حدیث میں اس کے عمل سے بھی مدد لی جاتی تھی۔ (تاریخ ابی زرعہ الدمشتی) امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ ’’التعقبات علی الموضوعات‘‘ میں فرماتے ہیں: اہل علم کے قول اور تعامل کے ساتھ حدیث ضعیف ضعف سے نکل کر صحیح اور قابل عمل ہوجاتی ہے۔ اگرچہ اس کی سند لائق اعتماد نہ ہو۔ بہت سے اہل علم کا یہ قول ہے۔
۳۔ تعدد اسناد:۔
ضعیف حدیث متعدد سندوں سے مروی ہو تو وہ حسن لغیرہ ہوجاتی ہے۔
۴۔ مجتہد کا استدلال:۔
علامہ شامی فرماتے ہیں کہ مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کر لے تو اس کا استد لال بھی حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ جیسا کہ ’’تحریر‘‘ میں امام ابن ہمام نے تحقیق فرمائی ہے۔ [43]
۵۔ اہل علم کا عمل:۔
علماء و صلحا کے عمل سے بھی حدیث کی صحت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ امام حاکم نیشا پوری صلوٰۃ التسبیح کی صحت پر استدلال کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ جس چیز سے اس حدیث کی صحت پر استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اتباع تابعین سے لے کر ہمارے اس دور تک تمام ائمہ اس پر ہمیشگی کے ساتھ عمل کرتے رہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتے رہے۔ جن میں عبد اللہ ابن مبارک بھی ہیں۔
۶۔ کشف:۔
اہلِ کشف کا کشف بھی ضعیف حدیث کو صحت کے درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ جیسا کہ شیخ ابن عربی کا یہ واقعہ کہ انہیں یہ روایت پہنچی کہ جو ستر ہزار مرتبہ کلمۂ طیبہ پڑھ لے تو اس کی اور جس کو ان کا ثواب بخشا گیا اس کی بھی مغفرت کردی جاتی ہے۔ آپ اس حدیث کو ضعیف سمجھتے تھے۔ آپ کے پاس اتنے کلمے پڑھے ہوئے تھے۔ ایک دعوت میں پہنچے، ایک نوجوان اچانک رونے لگا۔ معلوم کرنے پر بتایا کہ میری والدہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ شیخ ابن عربی نے دل ہی دل میں ستر ہزار کلمۂ طیبہ کا ثواب اُس کی ماں کو بخش دیا تو وہ نو جوان ہنسنے لگا اور کہا کہ میری والدہ اب اچھی حالت میں ہیں۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی صحت کو اس جوان کے کشف سے اور اس جوان کے کشف کی صحت کو اس حدیث کی صحت سے جان لیا۔ [44]
اھل علم کا اتفاق:۔
جس حدیث کے مفہوم و مدلول پر علماء کا اتفاق ہوجائے تو وہ بھی حدیث مقبول ہوجاتی ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جس حدیث کے مدلول پر علماء متفق ہوں وہ حدیث مقبول ہوتی ہے اور اس کے تقاضہ پر عمل کرنا واجب ہے۔ ائمہ اصول نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ [45]
۸۔ صرف حدیث ضعیف میسر ہو:۔
علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ جب کسی باب میں حدیث ضعیف کے علاوہ کوئی اور حدیث نہ ہو تو امام اسحاق علیہ الرحمہ نے حدیث ضعیف سے استدلال کیا ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کی اتباع کی ہے۔ امام ابو حنیفہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ [46]
یہ اور ان کے علاوہ کچھ اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے حدیث ضعیف ضعف سے نکل کر حسن بلکہ صحیح تک ترقی کرجاتی ہے۔ لہٰذا کسی حدیث کی سند کے سلسلہ میں ائمہ جرح و تعدیل کلام، طعن اور جرح کر کے اس کے ضعف کو سند اثابت بھی کردیں تو اس سے ہر گز یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث قابل عمل نہ رہی یا یہ کہ وہ موضوع ہوگئی۔ اس لیے کہ حدیث صحیح اور موضوع کے درمیان بہت سے درجے ہوتے ہیں۔
غیر مقلدین اور احادیث ضعیفہ:۔
غیر مقلدین اس سلسلہ میں بہت متشدد واقع ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے علمائے جرح و تعدیل میں سے کسی ایک جملہ بھی کسی درجہ کی بھی کتاب یا کتبیہ میں پڑھ لیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ان کی بانچھیں اس طرح کھل جاتی ہیں جیسے کہ کوئی بہت بڑا میدان مار لیا ہو۔ لہٰذا اسی خوشی میں مدہوش ہوکر بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے وہ اس کو باطل، موضوع اور جھوٹی قرار دے دیتے ہیں۔ خواہ وہ حدیث ضعیف فضائل اعمال یا مناقب ہی سے متعلق کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مقلدین نے صحابہ کرام کی فضیلت اور اُن کو اپنا ھادی و رہنمائی ماننے کی دعوت پر مشتمل اس حدیث پاک اصحابی کالنجوم کا بھی شد و مد کے ساتھ رَدّ کرنا شروع کر دیا۔ ابن حزم اور البانی کے علاوہ کسی نے بھی اس حدیث کو موضوع قرار نہ دیا بلکہ اگر کسی کا کوئی کلام موجود ہے بھی تو اس کا تعلق صرف اس کے ضعف سے ہے۔ انہیں دونوں کی اتباع کرتے ہوئے موجودہ زمانے کے غیر مقلدین وہابیوں نے بھی اس حدیث پاک کو موضوع قرار دے ڈالا۔
چونکہ آج ہماری نئی نسل کے علماء زیادہ انٹرنیٹ وغیرہ پر اپ لوڈ کتابوں کے پڑھنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ یا خوبصورت انداز کے ساتھ چھپی ہوئی اُن کتابوں کا کہ جو زیادہ تر وہابیہ کے مکتبوں سے ان کے غیر مقلد محققین کی تحقیق کے ساتھ شائع ہو رہی ہیں۔ وہ اپنے محقق نسخوں میں تحقیق کے نام پر ایسی حدیثوں کو کہ جن کی سندوں کے سلسلہ میں کابر ائمہ کے بہت سہل اور ہلکے الفاظ سے جرح و طعن اور کلام وارد ہوا ہے۔ خواہ سے دوسرے ائمہ نے رد ہی کیوں نہ کر دیا ہو۔ اُن کا سہارا لے کر انہیں باطل، موضوع اور مکذوب کہہ کر خاصا ردّ کرنے پر اپنی پوری تحقیق کا زور صرف کر دیتے ہیں۔ ان کی اس تحقیق سے دھوکا کھا کر فضائل و مناقب میں وارد ایسی احادیث کریمہ پر وہابیہ کے علاوہ اب ہمارے اپنے کچھ جدید فکر رکھنے والے علماء بھی کلام کرنے لگے ہیں۔
الصحابۃ نجوم الاھتداء کا سبب تالیف:۔
تحقیق کے نام پر ان وہابی محققین نے جن احادیث کریمہ کو تختۂ مشق بنایا ہے ان میں سے ایک حدیث پاک یہی ’’اصحابی کالنجوم‘‘ بھی ہے۔ جسے دیگر ائمہ کے ساتھ حضرت قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ’’الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ‘‘ میں نقل فرمایا ہے۔ اس کو پروفیسر طٰہٰ عبد الرؤف کی تحقیق، تخریج اور تعلیق و تحشیہ کے ساتھ سلفی ذہن و فکر رکھنے والے مکتبوں نے از سر نو شائع کر کے انٹر نیٹ وغیرہ کے ذریعہ پوری دنیا میں عام کیا ہے۔ اس حدیث کے اوپر مذکورہ پروفیسر نے سلفیوں، وہابیوں اور ابن حزم کی اتباع میں جو حاشیہ لگایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث اصحابی کالنجوم موضوع ہے۔ پھر اس کے موضوع ہونے پر دلیل کے طور پر امام ذہبی کی اُس گفتگو کا حوالہ دیا کہ جو میزان میں جعفر بن عبد الواحد ہاشمی کے حالات کے تحت درج ہے۔ اس کے ساتھ ہی امام دارقطنی کے حوالے سے ’’یضع الحدیث‘‘ (وہ حدیث گڑھتا ہے) نقل کیا۔ ابو زرعہ کا یہ قول بھی نقل کیا کہ جو جعفر کے حوالے سے اُن سے وارد ہو کہ ’’روی احادیث لا اصل لھا۔ وذکر ھٰذا الحدیث من بلایاہ‘‘ یعنی جعفر نے بے اصل حدیثیں روایت کی ہیں نیز ابو زرعہ نے جعفر کی مذکورہ روایت کو بھی اس کی ’’بلایا‘‘ میں شمار کیا ہے۔
محشی مذکور نے مذکورہ بالا الفاظ جرح سے اس حدیث کے موضوع ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے اس کا ردّ و ابطال کرنے، اس حدیث پر لگے الزام وضع کو دفع کرنے، اس حدیث کے حجت ہونے، اس کے معمول بہا ہونے، تلقی بالقبول کی وجہ سے درجۂ ضعیف سے درجۂ حسن تک ترقی کرنے اور اس کے متن و مفہوم کا علمائے متقدمین و متأخرین کے درمیان شہرت پذیر ہونے کو عقلی و نقلی دلائل سے ثابت کرنے کے لیے حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فصیح عربی زبان میں ’’الصحابۃ نجوم الاھتداء‘‘ کے نام سے ایک مختصر مگر جامع رسالہ تحریر فرمایا۔ یہ رسالہ ۴۷؍ صفحات پر مشتمل ہے جو ’’دار مقطم للنشر والتوزیح سے ۲۰۰۹ء میں صیام ابو سھل نجاح عوض کی تحقیق و تالیف کے ساتھ مصر سے شائع ہوا۔ صفحہ نمبر ۹ سے ۱۴ تک محقق رسالہ کا ایک عمدہ مقدمہ ہے۔ صفحہ ۱۵ سے ۱۸ تک محمد خالد ہندی کے قلم سے تحریر کیا ہوا سرکار تاج الشریعہ کا ایک جامع تعارف ہے۔ اصل رسالہ صفحہ نمبر ۱۹؍ سے شروع ہوکر صفحہ ۴۷ پر ختم ہوتا ہے۔
حضرت تاج الشریعہ کی فنی مہارت:۔
فن حدیث اور اس کے متعلقہ فنون میں سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی اگر مہارت تامہ دیکھنا ہو تو دلیل کے طور پر یہی مختصر رسالہ ہی کافی ہے۔ آپ نے اس رسالے میں ’’نقد رجال‘‘ کے تعلق سے جو فاضلانہ بحث کی ہے اسے دیکھ کر یہ یقین ہوجاتا ہے کہ بلاشبہ آپ وارث علوم اعلیٰ حضرت تھے۔ اگر کسی نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فن حدیث سے متعلق مباحث و رسائل خاص کر ’’الھاد الکاف‘‘، ’’تقبیل الابہامین‘‘، ’’حاجز البحرین‘‘ اور ’’شائم العنبر‘‘ جیسے رسائل کا مطالعہ کیا ہے تو وہ ’’الصحابہ نجوم الاھتداء‘‘ پڑھ کر ضرور یہ نتیجہ اخذ کرے گا کہ اس رسالے کی ہر بحث، اس کی ہر بحث کی ہر سطر اور اس کے ہر ہر لفظ میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، سرکار حجۃ الاسلام، سرکار مفتی اعظم ہند اور سرکار مفسر اعظم ہند کے علوم و فنون کے جلوے نظر آتے ہیں۔
سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے سلفی ذہن رکھنے والے معاصر محققین کا جس انداز میں روایتاً اور درایتاً تعاقب کیا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ اس حدیث پر الزام وضع کو آپ نے ۷؍ وجوہات سے دفع فرمایا ہے۔
وجہ اول:۔
چونکہ محشی مذکور نے اس حدیث کے موضوع ہونے پر امام دار قطنی کے قول ’’یضع الحدیث‘‘ کو دلیل کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس کی تردید کے لیے آپ نے سب سے پہلے ملا علی قاری کی شرح شفاء سے وہ عبارت من و عن نقل فرمائی ہے کہ جسے ہم ما قبل میں بیان کر آئے ہیں۔ اس عبارت کو نقل کر کے آپ نے اس سے دو نتیجے اخذ فرمائے۔
۱۔ بقول ملا علی قاری، دار قطنی نے خود ہی اس حدیث کو روایت کیا مگر اُس پر موضوع ہونے کا حکم نہ لگایا۔ بقول محشی اگر دار قطنی نے اس حدیث کو موضوع کہا ہوتا تو حضرت ملا علی قاری اس کو ضرور نقل فرماتے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دار قطنی کے نزدیک یہ حدیث موضوع نہیں ہے اور یضع الحدیث کا محمل اور اس کی مراد کچھ اورہے۔
۲۔ ملا علی قاری نے اسی ضمن میں علامہ ابن عبد البرکا قول نقل فرمایا ہے کہ ’’یہ ایسی اسناد ہے کہ جس سے حجت قائم نہیں کی جاسکتی‘‘۔ اسی طرح انہوں نے بزار کا یہ قول بھی نقل کیا کہ ’’یہ حدیث منکر غیر صحیح ہے‘‘۔ ان دونوں حضرات کے مذکورہ دونوں اقوال سے ہر گز ہر گز اس حدیث کا موضوع ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس سے محض اتنا ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع نہیں۔ اسی ضمن میں ملا علی قاری نے ابن عدی کے حوالے سے یہ نقل فرمایا کہ ’’اس کی اسناد ضعیف ہے‘‘۔ ابن عدی کے اس قول سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ حدیث مرتبۂضعیف سے مرتبۂ وضع تک نہیں پہنچی ہے۔ اس حدیث کے ضعف کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ مؤید تو امام بیہقی کا وہ جملہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ’’اس کا متن مشہور ہے اور اس کی سندیں ضعیف ہیں‘‘۔ کیونکہ امام بیہقی کا یہ جملہ اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف، ضعف سے ترقی کر کے تلقی بالقبول کی وجہ سے درجۂ حسن کو پہنچ چکی ہے۔ اسی وجہ سے ملا علی قاری نے اپنی گفتگو کو اس جملہ پر ختم فرمایا تھا کہ ’’حدیث کثرت طرق کی وجہ سے ضعف سے ترقی کر کے درجۂ حسن کو پہنچ جاتی ہے‘‘۔
پھر اسی حدیث کے ضمن میں شفاء کی شرح نسیم الریاض میں علامہ خفاجی نے بھی دار قطنی کے حوالے سے یہ بتایا کہ انہوں نے بھی اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے۔ مگر علامہ خفاجی نے بھی دار قطنی کے حوالے سے اس کے موضوع ہونے کو ذکر فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں حضرات (ملا علی قاری، علامہ خفاجی) دار قطنی کے حوالے سے گفتگو کریں اور بقول محشی مذکور کہ دار قطنی نے اسے موضوع کہا تھا علامہ خفاجی نے اس کی ضرور صراحت فرمادی کہ ابن حزم نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔
وجہ ثانی:۔
محشی مذکور نے موضوع ہونے کے اپنے دعوے پر ابو زرعہ کا قول دلیل کے طور پر جو نقل کیا ہے کہ ’’اس نے بے اصل حدیثیں روایت کی ہیں‘‘، تو اس سے بھی اس حدیث کا موضوع ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ابو زرعہ کا مذکورہ قول حکم بالوضع کے باب میں صریح نہیں ہے۔ پھر لسان المیزان میں سعید بن عمر کے حوالے سے ابو زرعہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ سعید کا اُن سے جعفر کی کچھ مرویات کا مذاکرہ ہوا تو ابوزرعہ نے اُن میں سے کچھ حدیثوں سے اپنی نکارت و عدم معرفت کا اظہار کیا اور بعض کے تعلق سے صریح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ باطل و موضوع ہیں۔ ان کے ان دومتغائر اور مختلف جملوں اور حکموں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو زرعہ ’’لا اصل لہا‘‘ سے حدیثوں کا موضوع ہونا مراد نہیں لیتے۔ لہٰذا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ابو زرعہ کے قول لا اصل لہا کو اس حدیث جعفر کے موضوع ہونے پر دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ نیز ان کالا اصل لہا کہنا اُن کے اپنے علم و معرفت کی بنیاد پر ہے۔ جس سے یہ ہر گز لازم نہیں آتا کہ دوسروں کے نزدیک بھی اس کی اصل ثابت نہ ہو۔
وجہ ثالث:۔
جعفر کے حالات کے ضمن میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ بے اصل حدیثیں نقل کرتا ہے، ثقہ راویوں سے منکر حدیثیں لے کر آتا ہے نیز ابو حاتم کے حوالے سے اس کے قصہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر وضع سند اور احادیث کو سرقہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ بھی اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ وضع سے مراد ’’وضع سند‘‘ ہے نہ کہ ’’وضع متن سند‘‘ اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کیونکہ محدثین کرام بھی کسی حدیث کو سند کے موضوع ہونے کے اعتبار سے موضوع کہتے ہیں اور کبھی متن کے اعتبار سے لہٰذا جب وضع سند کے اعتبار سے کسی حدیث کو موضوع کہا جائے تو وہ حکم صرف اور صرف سند ہی تک محدود رہے گا متن تک نہ جائے گا۔
جعفر پر ایک جرح غیر مفسر بھی جاری کی گئی تھی۔ جس کے سلسلہ میں حضرت تاج الشریعہ علامہ ابن صلاح کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اسباب جرح کی تعیین کے سلسلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ ایسی صورت میں ایک فریق کے نزدیک وہ جرح قابل قبول ہوگی اور دوسرے کے نزدیک نہیں ہوگی لہٰذا اسباب جرح کا واضح طور پر ذکر ضروری ہے تاکہ یہ متعین ہوسکے کہ ان اسباب کی وجہ سے یہ جرح قابل قبول ہے یا نہیں۔
وجہ رابع:۔
پھر ما قبل میں ابو زرعہ کے حوالے سے جو یہ کہا گیا کہ اس کی کچھ حدیثوں کو انہوں نے باطل موضوع قرار دیا تو یہ بھی جملہ کئی معانی کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ انہوں نے یہ جملہ ان حدیثوں کے بارے میں بولا ہو کہ جن کا دار و مدار صرف جعفر پر تھا جس سے ہر گز یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی تمام حدیثیں ہی اسی طرح ہوں۔ لہٰذا جعفر کی وجہ سے خاص طور پر اس حدیث کے بارے میں موضوع ہونے کا گمان کرنا صحیح نہیں ہے۔
وجہ خامس:۔
محشی مذکور طٰہٰ عبد الرؤف نے اس حدیث کے موضوع ہونے کے اپنے دعوے کو علامہ ابن حجر کی جانب منسوب کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ علامہ ابن حجر نے اولاً اس حدیث کے اوپر محض ’’ضعیف واہ‘‘ کا حکم لگایا ہے۔ علامہ ابن حزم کے تعلق سے ضرور یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث موضوع باطل ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن حجر نے تو امام بیہقی کے قول کہ حدیث مسلم اس کے بعض معانی کی تائید کرتی ہے، سے ابن حزم کے دعوے کو باطل کیا ہے نہ یہ کہ خود وہ اس کو موضوع کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا طٰہٰ عبد الرؤف کا علامہ ابن حجر پر یہ ایک صریح اور جھوٹا الزام ہے۔
وجہ سادس:۔
محشی مذکور نے جعفر کی وجہ سے اس حدیث پر وضع کا حکم لگایا اور دار قطنی کے قول ’’یضع الحدیث‘‘ کا حوالہ دیا حالانکہ خود دار قطنی نے اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے۔ لہٰذا اگر جعفر والی سند سے اس حدیث کی اُن کے ذریعہ کی گئی تخریج ثابت ہوجائے تو اولاً اس بات سے ان کا قول ’’یضع الحدیث‘‘، ٹوٹ جائے گا، ان کے اس فعل تخریج سے کہ جو انہوں نے بغیر موضوع کہے اس کی تخریج فرمائی۔ ثانیاً اس تخریج سے تو جعفر کی توثیق ہوگی بالفرض توثیق نہ بھی مانی جائے تو کم از کم اس سے یہ تو ثابت ہو ہی گیا کہ جعفر کی حدیث لکھے جانے اور قبول کیے جانے کے لائق ہے۔ نیز ابن عدی کا قول کہ وہ حدیث سرقہ کرتا ہے اور ثقہ راویوں سے منکر حدیثیں لاتا ہے، یہ حکم بھی وضع سند کی طرف راجع ہے نہ کہ وضع متن کی طرف۔
محشی مذکور نے اس حدیث کے موضوع ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کے تعلق سے کہے گئے ابو زرعہ کے اس قول کے ’’انہ من بلایاہ‘‘ سے استدلال کیا ہے، یہ بھی قابل رد ہے۔ کیونکہ یہ بھی اپنے ظاہر پر محمول نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کا دار و مدار صرف جعفر پر نہیں نیز اس حدیث کی دوسری حدیث سے تائید بھی ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اسے موضوع کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ امام ذہبی اور ابن حجر نے میزان اور لسان المیزان میں جعفر کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جعفر کو اس بات کی قسم دلائی گئی تھی کہ وہ حدیث بیان نہ کرے گا اور نہ ’’حدثنا‘‘ کہے گا۔ اس سے بھی جعفر کے اوپر وضع حدیث بمعنی وضع متن کا حکم نہیں لگایا جاسکتا کیونکہ اس عبارت سے صراحۃً صرف یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اسے حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی اور اجازت حدیث کی نفی سے ارتکاب وضع ثابت نہیں ہوتا۔ نہ سند میں اور نہ متن میں۔ نیز حدیث بیان کرنے کی ممانعت جرح مبہم کے قبیل سے ہے۔ جو لائق اعتنا نہیں۔ اسی طرح ابن عدی نے جعفر کی حدیثوں پر جو یہ حکم لگایا ’’کلھا بواطیل‘‘ کہ سب کی سب باطل ہیں۔ یہ حکم بھی مجمل ہے کیونکہ محض اتنے سے یہ واضح نہیں ہو رہا کہ بطلان آیا سند کی جہت سے ہے یا متن کی جہت سے؟ اگر متن کی جہت سے ہے تو حکم وضع کا سبب کیا ہے؟ علامت وضع کیا ہے؟ نیز یہ موضوع کی کس قسم سے تعلق رکھتی ہے؟ بلاشبہ یہ محل محل تفصیل ہے جس میں اجمال ممنوع ہے۔
وجہ سابع:۔
اس حدیث کو موضوع بتانے والوں میں ابن حزم منفرد ہے۔ سب سے پہلے ا سی نے اس کے اوپر موضوع ہونے کا حکم لگایا اور اسی کی اتباع کرتے ہوئے قدیم و جدید سلفیہ اور وہابیہ بھی اسے موضوع بتانے لگے۔ محشی مذکور نے بھی اس حدیث پر وضع کا حکم لگانے پر ابن حزم ہی پر اعتماد کیا ہے۔ حالانکہ ابن حزم نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حارث بن غصین اور سلام بن سلیمان کی وجہ سے اس حدیث پر کلام کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ’’سلام بن سلیمان موضوع حدیثیں روایت کرتا تھا اور بلا شبہ یہ حدیث بھی انہیں موضوع حدیثوں میں سے ہے لہٰذا اس کی اسناد کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ روایت ساقط ہے‘‘۔
ابن حزم کا یہ دعویٰ کئی اعتبار سے قابل ردّ ہے کیونکہ اس کے ذریعہ عائد کردہ یہ حکم، سند سے متعلق ہے نہ کہ متن سے۔ جس پر قرینہ اس کا اگلا قول ہے کہ یہ روایت ساقط ہے۔ الخ نیز ابن حزم کا ’’ھذا منھا بلا شک‘‘ کا یہ دعویٰ ممنوع ہے کیونکہ یہ بنا دلیل ہے۔ پھر اس کے قول کا پہلا جملہ دوسرے جملے ہی سے منقوض ہے کیونکہ وہ خود آخری جملے میں اس کی سند کے ضعیف ہونے کا قرار کر رہا ہے۔ جبکہ ضعف سند ضعف متن ہی کو مستلزم نہیں چہ جائے کہ وہ کسی حدیث کے موضوع ہونے کو مستلزم ہو۔ مجہول ہونے کی وجہ سے حدیث ابن عمر کے دوراویوں عبد الرحیم اور زیدعمی کو متروک قرار دینے سے بھی زیادہ میں زیادہ اس حدیث کا ضعیف ہونا لازم آئے گا نہ کہ موضوع ہونا۔ بزار نے جو یہ کہا کہ ’’ھذا کلام لا یصع عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم‘‘ کہ یہ حدیث آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحیح نہیں۔ بزار کے اس قول سے اس حدیث کو موضوع ثابت کرنا یا اس کو باطل و کاذب کہنا یہ بھی باطل ہے کیونکہ بزار کے اس قول کا مفاد صرف اتنا ہے کہ یہ حدیث محدثین کی اصطلاح والی ’’حدیث صحیح‘‘ کے درجے تک پہنچی ہوئی نہیں ہے۔ کیونکہ صحت کی نفی سے تو کسی حدیث کاحسن نہ ہونا ہی ثابت نہیں ہوتا چہ جائے کہ یہ اس حدیث کے ضعیف یا موضوع ہونے کا افادہ کرے۔
· ان ساتوں وجوہات کی تفصیلات کو پڑھیں اور ان کے بین السطور میں پائے جانے والے فن حدیث اور فن جرح و تعدیل کے گراں قدر موتیوں کو چنیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تاج الشریعہ کی تحریروں اور ان کے بیان کردہ نکات میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا فیضان بھر پور انداز میں جھلک رہا ہو اور بلا شبہ حقیقت بھی یہی ہے۔
· ان ساتوں وجوہات کے ضمن میں محشی مذکور، ابن حزم اور سلفیوں کے اس دعوے کے ظاہر البطلان ہونے کی قلعی کھولنے کے بعد سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے ابن حزم کے کچھ اقتباسات نقل کر کے ہر ایک کا رد بلیغ فرمایا ہے۔ اخیر میں آپ نے یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ اس حدیث یا اس طرح کی دیگر روایتوں کو موضوع کہہ کر ردّ کرنے کے پیچھے ان سلفیوں کی ایک غرض فاسد کار فرما ہے اور وہ یہ کہ جب صحابہ کرام ہی مجروح ہوجائیں گے، ان کی عدالت ساقط کردی جائے گی۔ ان کی ان اقتدا ہی باطل ہوجائے گی تو تقلید کا دروازہ ہی سرے سے بند ہوجائے گا اور ہر شخص کو اجتہاد کرنے کی اتھارٹی مل جائے گی۔ صالحین کی تقلید کو چھوڑ کر عیاش، گمراہ اور دنیا داروں کی تقلید کا قلادہ امت مسلمہ کے گلے میں آسانی کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ جبکہ مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اجتہاد کرنے اور ان کے اجتہاد کی تقلید کرنے کا حکم خود آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس کی سب سے واضح دلیل ہے۔
· ابن حزم اور ان کے متبعین کی جسارت، بے ادبی اور گستاخی کی نظیر پیش کرتے ہوئے حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے صحابی رسول حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس کی گستاخانہ گفتگو کو نقل فرماتے ہوئے کہا ہے کہ ابن حزم نے حضرت ابو طفیل کو مقدوح قرار دیا اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ مختار کے جھنڈا بردار تھے جو رجعت کا عقیدت رکھتا تھا۔
جبکہ ماقبل میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن و حدیث کے ظاہر اور اجماع سے یہ ثابت ہے کہ تمام صحابہ عادل وثقہ ہیں۔ اس نے حضرت ابو طفیل ہی کی عدالت کو ساقط نہ کیا بلکہ اس کی وجہ سے تمام صحابہ کی عدالت کو ساقط کرنے کی اس نے جسارت و کوشش کی ہے اور یہی اس کا مقصود بھی ہے بلکہ تمام وہابیہ ہی کی یہ کوشش ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں سے صحابہ کرام کی عظمت و وقعت کو ختم کر دیا جائے۔
· اخیر میں حضرت تاج الشریعہ نے ایک بہت ہی کار آمد نسخۂ کیمیا عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی حدیث اصول شرع سے متصادم نہ ہو تو اس پر عمل پیرا ہوجانا چاہیے کہ اگر وہ حقیقت کے اعتبار سے ثابت شدہ حدیث ہے تو عمل کا بھی ثواب اور حدیث پرعمل کرنے کا بھی اجر۔ بالفرض نفس الامر میں وہ حدیث نہ بھی ہو تب بھی کسی اچھے کام کرنے میں کیا نقصان ہے۔ عقلمندی کا تقاضا یہ نہیں کہ عمل کرنے کے لیے صحت سند کا انتطار کرے کیونکہ جب تک صحت سند کا ثبوت ملے گا تب تک تو عمل کرنے کا وقت ہی نکل جائے گا۔ بلکہ دانشمندی یہ ہے کہ جب کوئی اچھی بات ملے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دے کہ ہر اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔
اس اصول کو ذہن نشیں کرانے کے لیے آپ نے ایک بہت عمدہ مثال پیش فرمائی ہے کہ
’’شدت مرض کے شکار آدمی کو اگر کوئی شخص کسی حکیم کے حوالے سے کوئی نسخہ بتائے تو عقلمندی یہ ہے کہ وہ اپنے مرض کو دور کرنے کے لیے فوراً اس پر عمل کرتے ہوئے اس دوا کا استعمال کرے۔ دانشمندی یہ نہیں کہ وہ اس بات کی تلاش میں پڑے کہ یہ نسخہ اس حکیم سے مجھ تک کس سند کے ذریعہ سے پہنچ رہا ہے۔ اس کے پہنچانے والے کیسے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ اس کی تلاش میں پڑے گا تو جان سے ہاتھ دھوم بیٹھے گا۔ یہ تو اس مثل کے مطابق ہوا کہ جب تک زہر کاٹنے والی تریاق نامی دوا عراق سے آئے گی تب تک تو سانپ کا ڈسا ہوا شخص اس دنیا سے ہی رخصت ہوجائے گا‘‘۔
بلاشبہ یہ پورا سالہ ہی فن حدیث، نقد رجال، فن اسماء الرجال، فن جرح تعدیل کے علاوہ فن مناطرہ کے آبدار موتیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث، درایت حدیث، روایت حدیث کے ساتھ ائمہ جرح و تعدیل کے الفاظ جرح کے حقیقی مفہوم، ان کے محمل اور ان کی مراد کیا ہے؟ ان سب باتوں میں حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا پایہ کس قدر بلند تھا۔ آپ نے اپنی بے مثال علمی خدمات کے ذریعہ یہ ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت اور مشائخ خانوادۂ رضویہ کے علوم و فنون، معرفت و حکمت اور روحانیت کے آپ ہی بلا شبہ سچے وارث و امین تھے۔
[1] ۔ فتح المغیث للسخاوی، جلد ۳ ؍ صفحہ ۸۶ بحوالہ الاصابہ ص ۷ جلد ۱ ۔
[2] ۔ الفتح ۲۹ ۔
[3] ۔ کنز الایمان۔
[4] ۔ الحشر ۸ ۔ ۹ ۔
[5] ۔ کنز الایمان۔
[6] ۔ الانفال۷۴۔
[7] ۔ کنز الایمان ۔
[8] ۔ الفتح ۱۸ ۔
[9] ۔ کنز الایمان۔
[10] ۔ التوبۃ ۱۱۹ ۔
[11] ۔ کنز الایمان۔
[12] ۔ التوبۃ ۱۰۰۔
[13] ۔ کنز الایمان۔
[14] ۔ البقرۃ ۱۴۳۔
[15] ۔ کنز الایمان۔
[16] ۔ آل عمران ۱۱۰۔
[17] ۔ کنز الایمان۔
[18] ۔ الحج ۷۸۔
[19] ۔ کنز الایمان۔
[20] ۔ النمل ۵۹ ۔
[21] ۔ کنز الایمان۔
[22] ۔ بخاری، کتاب فضائل الصحابۃ۔
[23] ۔ ترمذی جلد ۵ ؍ ۶۵۳ کتاب المناقب۔
[24] ۔ مسلم جلد ۳ ؍ ۱۹۶۱ کتاب فضائل الصحابۃ۔
[25] ۔ مسلم، کتاب فضائل الصحابۃ۔
[26] ۔ مرأۃ المناجیح جلد ۶ ؍ صفحہ ۳۳۹ ۔
[27] ۔ مرأۃ المناجیح، جلد ۷ ۔
[28] ۔ ماخوذ از فتاویٰ حامد یہ صفحہ ۱۲۶ ، ۱۲۷ مطبوعہ رضوی کتاب گھر دہلی۔
[29] ۔ ماخوذ از بہار شریعت جلد اول صفحہ ۲۵۶ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کراچی ۔
[30] ۔ ماخوذ از نور الانوار صفحہ ۹ ؍ مطبوعہ مجلس برکات۔
[31] ۔ الاصابۃ جلد اول مقدمہ مفہوماً و اختصاراً۔
[32] ۔ الاصبابۃ جلد ۱ ، مقدمۃ التحقیق مفھوماَ واختصاراَ۔
[33] ۔ مرأۃ المناجیح جلد ۶ ؍ صفحہ ۳۴۵ ، باب مناقب الصحابہ۔
[34] ۔ مرقاۃ باب مناقب الصحابۃ۔
[35] ۔ جلد ۳ صفحہ ۴۲۵ ۔ مطبوعہ برکات رضا پور بندر گجرات۔
[36] ۔ مفہوماً و اختصاراً۔
[37] ۔ ماخوذ از: مرقاۃ باب مناقب الصحابہ۔
[38] ۔ نسیم الریاض جلد ۳ ؍ ص ۴۲۳ ؍ ۴۲۴ مطبوعہ (مرکز اہلسنت برکات رضا پور بندر گجرات)۔
[39] ۔ شرح شفاء الملا علی قاری ہامش نسیم الریاض جلد ۳ ص ۴۲۳ ، مطبوعہ گجرات۔ شرح شفاء الملا علی قاری ہامش نسیم الریاض جلد ۳ ص ۴۲۳ ، مطبوعہ گجرات۔
[40] ۔ نسیم الریاض مع الشفاء و مع شرح الشفاء لملا علی قاری مطبوعہ پور بندر، گجرات جلد ۳ صفحۃ ۴۲۳ ۔ ۴۲۴ ۔
[41] ۔ مقدمۃ المحقق من الصحابہ کالنجوم صفحہ ۱۱ تا ۱۳ ۔
[42] ۔ شرح فقہ اکبر صفحہ ۱۱۶ مطبوعہ دار الایمان۔
[43] ۔ ردالمختار جلد ۴ صفحہ امطبوعہ استانبول۔
[44] ۔ مرقا جلد دوم صفحہ ۹۸ ؍ مکتبہ امدادیہ ملتان۔
[45] ۔ النکت علی کتاب ابن الصلاح جلد ۱ صفحہ ۴۹۴ ، مطبوعہ احیاء التراث۔
[46] ۔ فتح المغیث، جلد ۱ صفحہ ۲۳۳ ، مطبوعہ دار الامام۔