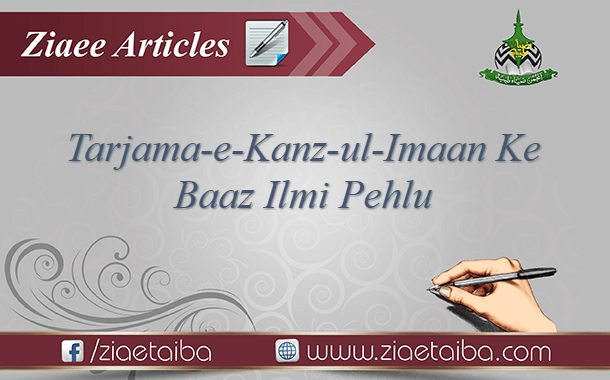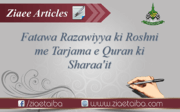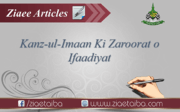ترجمۂ کنز الایمان کے بعض علمی پہلو
ترجمہ کنز الایمان کے بعض علمی پہلو
مولانا محمد حنیف خان رضوی، بریلوی
سیدنااعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی قدس سرہ العزیز کے ترجمۂ قرآنکنزالایمان کواللہ رب العزت جل جلالہ نے وہ شرف ِ قبولیت عطافرمایا کہ ہردورمیں اپنوں اور غیروں نے اس کی جامعیت ومعنویت،سلاست و روانی،اوراردوادب میں انفرادیت کا خطبہ پڑھا۔
اس میں شبہ نہیں کہ غیروں میں منصف مزاج لوگوں کے ساتھ ساتھ معاندین بھی ہر زمانہ میں رہے اور آج بھی ہیں،لیکن اس فرقہ عنادیہ کانہ پہلے کوئی علاج تھااور نہ آج ہے،لہٰذا اگر کوئی شخص بغرضِ عنادکنزالایمانکونشانہ ستم بنائے تواس سے اس کی حقانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ماضی قریب میں کچھ اسی طرح کے لوگوں نےاس ترجمہ کے ساتھ معاندانہ رویہ اپنایاتواس کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوا۔بلامبالغہ آج بھی اس کی مقبولیت کاآفتاب نصف النہار پر ہےاورچشم بددور،اس کی مقبولیت عام میں اضافہ ہوتاہی جائے گا۔
اس کے ساتھ یہ بات بھی مسلم ہے کہ اس کی پذیرائی بلاوجہ نہیں بلکہ اس ترجمہ کے اندر زبان وبیان کی ندرت،فصاحت و بلاغت کی شان ، عقائدواحکام اور اصول و قواعدکی رعایت، عشق و محبت کی چاشنی وحلاوت، حتیٰ کہ روحِ قرآن کی نورانیت جیسی صفاتِ بدیعہ جلوہ بار ہیں۔
ترجمہ کے اندرقرآنی علوم کوپورے طورپر ملحوظ رکھاگیاہےآیات کے موقع و محل کو مدنظر رکھتےہوئے نظمِ قرآن کے معانی اس طرح چن چن کےلائے گئے ہیں جیسے برسوں ان پر تحقیقی کی گئی ہو، حالانکہ ترجمہ کا پس منظربتاتاہے کہ پوراترجمہ بصورتِ املاتحریر کرایاگیاہے اور املا کرانے کے لیے بھی کوئی مستقل اطمینان کا وقت نہیں تھابلکہ بوقتِ قیلولہ جب کہ اس وقت کتابوں کی طرف نہ توجہ نہ مرجعت،فقط آیات کو سن کر یونہی فی البدیہ اور برجستہ بولا گیااور حضرت صدرالشریعہ علہ الرحمتہ والرضوان نے لکھ لیا۔
اس پس منظرکوسامنے رکھ کر حاملینِ علم ودانش جب اس کامطالعہ کریں گےتووہ اس کی خوبیوں کے تعلق سے خراجِ عقیدت پیش کیے بغیرنہیں رہ سکتے۔
دیگرمترجمین سے امتیازکے لیے یہ بہت بڑاانفرادی وامتیازی پہلو ہے کہ امام اہل سُنّت نے اپنی ہنگامی مصروفیات میں سے ایک ضمنی وقت اس کے لیے نکالالیکن قوم و ملت کواردوزبان میں ایساایمانی خزانہ عطافرمایاجو نادرالمثال،علمی تحقیقات سے مالامال اور عرفانی نکات کا بحر ِذخّار ہے۔
قرآنِ کریم کی ہر ہر آیت میں لفظی و معنوی اعتبارسے جو حکمتیں پنہاں ہیں ان کو رسولﷺ کے سوا کماحقہ کوئی انسان نہیں بیان کرسکتا آپ کے علاوہ کوئی بھی جو کچھ بتائے گاوہ آپ کی تعلیمات سے یا آپ کے صدقہ وطفیل ملنےوالی عقلِ سلیم کے ذریعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ سلسلہ جاری ہوااور آج تک جاری ہےاور آئندہ بھی اسی طرح جاری رہےگا۔زیرِمطالعہ مضمون میں راقم الحروف نے چندمقامات سے آیات کے ترجمہ کے بعض علمی پہلومتقدمین و متاخرین کی عربی تفاسیرکی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی ہےجس سے ترجمۂ قرآن کے سلسلہ میں اس بات کااندازہ لگایاجاسکتاہےکہکنزالایمان کامعیارکتنابلندہےاور یہ اپنے اندرکس قدرخوبیاں رکھتا ہے۔
مقامِ اوّل:
سورۂ بقرہ کی دوسری آیت کا جزہے:
ذٰلِكَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ ۚۖۛ فِیْہِ
ترجمہ:وہ بلند رتبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی جگہ نہیں۔(کنزالایمان)
یہاں(ذلک)کے سلسلے میں مفسرین نے نہایت تفصیلی گفتگوکی ہے،اصل سوال یہ ہے کہ قرآن کریم جو موجود ہے یہاں(ذالک)سےاس کی جانب اشارہ ہے جب کہذلکاسم اشارہ اہل عرب کے عرف میں بعیدکےلیے بولاجاتاہے،لہٰذایہاں عرف عرب کے مطابق ھذا آناچاہیےتھا،پھریہاں وہ کونسانکتہ ہے جس کے پیش نظرھذاکے بجائےذلکلایاگیا۔
دوسراسوال یہ ہے کہ قرآنِ کریم کے بارے میں بہت سے لوگ پہلے دن سے شک و شبہ میں مبتلاہیں اور آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں پھربالکلیہ نفی فرماناکہاس میں کوئی شک نہیں بظاہر خلافِ واقع معلوم ہوتاہے۔
ان دونوں سوالوں کے جواب سیدنااعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اپنے ترجمہ کے اندراس بالغ نظری اور عمیق نگاہی سے دیےہیں جس کی جتنی مدح کی جائے کم ہے،جب کہ دوسرے متداول ترجمے اس سے یکسرخالی ہیں۔
ملاحظہ کریں کہ آیت کا ترجمہ اس طرح فرمایاہے:
وہ بلندرتبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی جگہ نہیں
یعنی ذلک اسم اشارہ یہاں بُعدِ حقیقی کے لیے نہیں بلکہ بُعد رتبی کے لیے ہے، اور جب اس کا مرتبہ بلند ہےتو وہاں تک کسی کا شک و شبہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔یعنی وہ اپنی رفعت وبلندی کے سبب ریب اورشک سے پاک ہے،اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، یہ لوگوں کی ہٹ دھرمی اورکج فہمی ہے کہ اس میں شک کرتے اور شبہات پیش کرتے ہیں۔
خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآنِ کریم کی عظمت کا اظہاراوراس کا شک وشبہ سے بالاترہونادونوں کا ترجمہ کنزالایمان سے بخوبی پتہ چل رہاہے۔
سیدنااعلیٰ حضرت قدس سرہ کے اس فصیح وبلیغ ترجمہ کی تائید مفسرینِ کرام کی مستند تفاسیر میں موجود ہے۔
مندرجہ ذیل تفاسیر کو ملاحظہ کیجئےاور ترجمۂ کنزالایمان کی حقانیت کی داد دیجئے۔
تفسیرِ کبیر میں ہے:
وسابعھا أن القرآن لما اشتمل علی حکم عظیمۃ وعلوم کثیرۃ یتعسر إطلاع القوۃ البشریۃ علیھا بأسرھا والقرآن وإن کان حاضرًا نظرًا إلی صورتہ لکنہ غائب نظرا إلی أسرارہ وحقائقہ فجاز أن یشارالیہ کما یشار الی البعید الغائب۔
(جلد1،ص259)
ذلکاسمِ اشارہ بعیدکویہاں لانے کی ساتویں وجہ یہ ہے کہ قرآنِ کریم چونکہ ایسی عظیم حکمتوں اور اتنےکثیرعلوم پر مشتمل ہے کہ بشری طاقت کے لیے ان سب کا احاطہ دشوار ہے،چنانچہ قرآن اگرچہ اپنی ظاہری صورت میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے حاضرہے لیکن اپنے اسراروحقائق کے اعتبارسے نظروں سے غائب ہے،لہٰذایہاں وہ اسم اشارہ لایاگیا جس سے غائب بعید کی طرف اشارہ کیاجاتاہے۔
اس کے بعدلاریب فیہکی تفسیرمیں ہے:
المراد أنہ بلغ فی الوضوح إلی حیث لاینبغی لمرتاب أن یرتاب فیہ والأمرکذلك لأن العرب مع بلوغھم فی الفصاحۃ إلی النھایۃ عجزوا عن معارضۃ أقصر سورۃ من القرآن وذلك لیشھد بأنہ بلغت ھذہ الحجۃ فی الظھور إلی حیث لایجوز للعافل أن یرتاب فیہ۔
(تفسیرکبیر،ج1،ص266)
یہاں مراد یہ ہے کہ قرآنِ کریم اپنی نہایت وضاحت کے سبب اس اعلیٰ مقام پر ہے کہ اس نے کسی شک کرنےوالے کے لیے اس بات کی گنجائش ہی نہیں رکھی کہ وہ اس میں شک کرے،یہی وجہ ہے کہ عرب اپنی غایتِ فصاحت کے باوجوداس کی چھوٹی سی سورت کا بھی مقابلہ نہ کرسکے،اس تناظرمیں یہ بات بالکل عیاں ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں۔
تفسیرِروح البیان میں ہے:
فالجواب أن ھذ ا نفی الریب عن الکتاب لاعن الناس والکتاب موصوف بأنہ لایتمکن فیہ ریب فھو حق صدق معلوم ومفہوم شك فیہ الناس أو لم یشکوا۔
(جلد1،ص33)
یہاں شک کی نفی کتاب سے ہے نہ کہ لوگوں سے،اورکتاب کی شان یہ ہے کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں،لہٰذا یہ کلام حق و صداقت پرمبنی ہے اور اس کی یہ صفت یقینی و واقعی ہے، خواہ اس کے بارے میں لوگ شک میں گرفتارہیں یانہیں۔
تفسیرِجلالین اور اس کے حاشیہ صاوی میں ہے:
والإشارۃ بہ للتعظم،أی والقرآن وإن کان قریبا منا إلا أنہ مرفوع الرتبۃ وعظیم القدر من حیث أنہ منزہ عن کلام الحوادث۔
(ج1،ص11)
اورذلکسےاشارہ تعظیم کے لیے ہے،یعنی قرآنِ کریم اگرچہ ہم سے قریب ہے مگر اس اعتبارسے اس کامرتبہ بہت بلندہےکہ یہ کلام حوادث کی آمیزش سے منزہ وپاک ہے۔
تفسیرِارشادالعقل السلیم میں ہے:
ذلك ذا اسم اشارۃ واللام عماد جیء بہ للدلالۃ علی بعد المشارالیہ والکاف للخطاب والمشارالیہ ھو المسمی فانہ منزل منزلۃ المشاھد بالحسن البصری وما فیہ من معنی للبعد مع قرب العھد بالمشارالیہ لایذان بعلو شانہ وکونہ فی الغایۃ القاصیۃ من الفضل والشرف۔
(ج1،ص27)
ذلکمیںذااسم اشارہ ہے اورلامحرفِ عماد،یہ مشارالیہ کے بُعدپردلالت کے لیے لایاگیاہے،اورکبرائےخطاب ہے، یہاں مشارالیہ مسمی ہے اور یہ محسوس مشاہدکی منزل میں قراردیاگیاہے،اور مشارالیہ قریب ہونے کے باوجوداشارہ بعیداس لیے لایاگیا تا کہ اس کی علوِ شان پر آگاہی بخشی جائےاور یہ بتایاجائے کہ یہ فضل و شرف میں غایت نہایت پر ہے۔
دوسرے مقام پر ہے:
ومعنی نفیہ عن الکتاب أنہ فی علو الشان وسطوع البرھان بحیث لیس فیہ مظنۃ أن یرتاب فی حقیقتہ وکونہ وحیا منزلا من عند اللّٰہ تعالیٰ لا أنہ لایرتاب فیہ أحد أصلا۔
(ج1،ص29)
قرآنِ کریم سے شک کی نفی اس طورپرہےکہ یہ اپنی شان کی بلندی اور دلیل وبرہان کی تابانی میں اس منزل پرہے کہ اس کی حقیقت اور وحی منزل ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں، یہ مطلب نہیں کہ اس میں شک کرنے والاہی موجود نہیں۔
تفسیرِروح المعانی میں ہے:
والإشارۃ بذ الك للتعظیم وتنزیل البعد الرتبی منزلۃ البعد الحقیقی کما فی قولہ تعالی (فَذٰلِکُنَّ الَّذِیْ لُمْتُنَّنِیْ فِیْہِ) کما أختارہ فی المفتاح، أو لأنہ لما نزل عن حضرۃ الربوبیۃ وصار بحضرتنا بعد۔
(ج1،ص174)
ذلکسے اسمِ اشارہ تعظیم کے لیے ہے،یعنی بُعدِ رتبی کوبُعدِحقیقی کی منزل میں قراردیا گیا، جیسے آیت کریمہ:
(فَذٰلِکُنَّ الَّذِیْ لُمْتُنَّنِیْ فِیْہِ)
میں صاحب مفتاح کا یہی مختارہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتاہے کہ جب بارگاہ خداوندقدوس سے ہمارے پاس قرآن آیاتو بعید قرار پایا۔
نیزدوسرے مقام پر ہے:
ونفی سبحانہ الریب فیہ مع کثرۃ المرتابین۔لاکثرھم اللّٰہ تعالیٰ۔علیٰ أنہ فی علو الشان وسطوع البرھان بحیث لایرتاب العاقل بعد اللنظر فی کونہ وحیا من اللّٰہ تعالیٰ۔
(ج:1،ص:177)
قرآنِ کریم میں شک کرنے والے بے شمارلوگ ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو نیست ونابود فرمائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ریب کی نفی بایں معنی فرمائی کہ قرآن اپنی رفعت، شان اور تابانی ،دلیل و برھان میں اس اعلیٰ مقام پر متمکن ہےکہ عقل مندغوروفکرکے بعد اس کو بخوبی سمجھ سکتاہے کہ یہ وحی ربانی ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کو دخل نہیں۔
تفسیرِحدائق الروح والریحان میں ہے:
إنما ھو نفی الریب عن الکتاب لاعن الناس
(ج1،ص107)
شک وارتیاب کی نفی کتاب سے ہے لوگوں سے نہیں۔
ان تمام تفاسیرکی وضاحتوں کو سامنے رکھیےاورپھرکنزالایمانکاترجمہ ملاحظہ کیجئے، معلوم ہوتا ہے کہ سب کا نچوڑ اور خلاصہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے چند الفاظ میں بیان فرمادیاہے۔
مقامِ دوم:
اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پرانعامات کوقرآن ِکریم میں متعدد مقامات پر بیان فرمایاہے:انہیں میں ایک یہ بھی کہ بنواسرائیل کو ان کے زمانہ میں ساری اقوام پر فضیلت دی،ارشاد ربانی ہے:
وَاَنِّیْ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ
ترجمہ:اور یہ کہ اس سارے زمانہ پر تمہیں بڑائی دی۔(کنزالایمان)
اس ترجمہ سے یہ بات عیاں ہے کہ بنواسرائیل کو تمام انسانوں میں فضیلت اوربڑائی صرف انہیں کے زمانہ میں تھی۔ہرزمانہ میں نہیں،ورنہ یہ آیت دوسری آیت:
کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ۔ الآیۃ
کے معارض و مخالف قرارپائے گی حالانکہ دونوں کامحمل اپنے اپنے مقام پر طے ہے، یعنی بنواسرائیل اپنے زمانہ میں سب سے افضل تھے اور حضور نبی کریمﷺ کی امت کوسب پر فضیلتِ مطلقہ حاصل ہے،یہ مضمون جس طرح آیات سے ثابت ہے اسی طرح اس کی وضاحت احادیثِ کریمہ میں بھی موجودہے۔اسی لیے تفاسیرمیں اس کی نشاندھی مفسرین ہرزمانہ میں کرتے آئے،مندرجہ ذیل تفاسیر ملاحظہ فرمائیں:
تفسیرِقرطبی میں ہے:
یرید علیٰ عالمي زمانھم
(ج1،ص419)
مراد یہ ہے کہ ان کے زمانہ میں۔
تفسیرِثعالبی میں ہے:
المعنی علیٰ عالمي زمانھم الذي کانت فیہ النبوۃ المتکررۃ، لأن اللّٰہ تعالیٰ یقول لأمۃ محمدﷺ: کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ۔الآیۃ
(ج1،ص233)
مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ فضیلت انہیں کے زمانہ میں تھی کہ ان کے خاندان میں لگاتار رسولوں کی آمد ہوتی رہی،ہرزمانہ میں ان کو یہ بڑائی حاصل نہیں،اس لیے کہ حضورنبی کریم ﷺ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشادفرمایا:
کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ۔الآیۃ
تفسیرِروح البیان اور حدائق الروح والریحان میں ہے:
أی فضلت آباءکم علیٰ عالمی زمانھم بمامنحتھم من العلم والایمان والعمل الصالح۔
(روح البیان،ج1،ص:128/حدائق الروح والریحان،ج1،ص:369)
یعنی تمہارے آباء واجدادکو ان کے زمانہ میں فضیلت حاصل رہی،کہ اللہ تعالیٰ نے علم،ایمان اور عمل صالح کی برکتوں سے نوازا۔
تفسیرِاعراب القرآن میں ہے:
وال فی العالمین للعھد لاللجنس لئلا یلتزم تفضیلھم علیٰ جمیع الناس والمرادعلیٰ عالمی زمانھم۔
(ج:1،ص:100)
العالمین میں الف لام برائے عہد ہے جنس کے لیے نہیں، تاکہ تمام لوگوں پر فضیلت نہ لازم آئے،
لہذاانہیں کے زمانہ کے لوگ مراد ہیں۔
تفسیرِبیضاوی اوراس کے حاشیہ شیخ زادہ میں ہے:
أی عالمی زمانھماشارۃ الیٰ جواب مایقال:کیف قیل فی حق من وجد فی زمان نزول ھذہ الآیۃ (وَاَنِّیْ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ) مع أن العالم اسم الجمیع مایعلم بہ وجود الصانع من الموجودات وتفضیلھم علی العالمین بھذ االمعنی یستلزم کونھم مفضلین علیٰ رسول اللّٰہﷺ وعلیٰ أصحابہ وأمتہ التی قال تعالی فی حقھم:( کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)ومن المعلوم بالضرورۃ أنھم لیسوا مفضلین علیہم؟وتقریر الجواب أن المفضل علیٰ العالمین حقیقۃ واصالۃ لیس ھو الموجودین فی زمان نزول ھذ ہ الأیۃ بل ھم الذین کانوا فی عصر موسی علیہ السلام، وبعد ہ قیل أن تغیرشریعۃ موسی علیہ السلام، والحکم علیھم بأنھم مفضلون علی العالمین انمایستلزم فضلھم علیٰ أھل زمانھم لاعلیٰ من سیوجد بعدھم لأن العالم اسم للموجود ومن سیوجد بعدھم من الصحابۃ والتابعین لھم من ھذہ الأمۃ لیسوا بموجودین فی زمان نسبۃ الفضل الیھم فلا یتناولھم مفھوم العالمین فلایلزم من تفضیل آباءھم الذین کانوا فی عصر موسیٰ علیہ السلام وبعد ہ قیل أن تغیرشریعتہ تفضیلھم علیٰ من سیوجد بعدھم من ھذ ہ الأمۃ۔
(تفسیربیضاوی مع حاشیہ شیخ زادہ،ج:2،ص:37)
یعنی ان کے زمانہ والوں پر،اس تفسیرمیں ایک جواب کی جانب اشارہ مقصود ہے سوال یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت ان لوگوں کو تمام عالموں پر کیسے فضیلت حاصل ہوئی جب کہ عالم ان تمام موجودات کانام ہے جن کے ذریعہ صانع عالم کی معرفت حاصل ہوتی ہے، چنانچہ ان کی تمام عالم پر فضیلت کا مطلب یہ ہوگاکہ یہ رسول اللہﷺ اور صحابہ کرام و جمیع امت محمدیہ سے افضل قرارپائیں حالانکہ حضورنبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی شان تونہایت ارفع و اعلیٰ ہے آپ کے طفیل آپ کی امت کو بھی دیگرامتوں پر فضیلتِ مطلقہ حاصل ہے کہ امتیوں کے حق میں آیت کریمہ:(کنتم خیرأمۃ أخرجت للناس)نازل ہوئی جس سے معلوم ہواکہ بنی اسرائیل کو امت محمدیہ پر فضیلت حاصل نہیں۔
اس کا جواب یہ ہے کہ تمام عالم سے مراداس آیت کے نزول کے وقت پائے جانے والے لوگ نہیں صرف وہی لوگ مرادہیں جوحضرت موسیٰ علیٰ نبیناعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں موجود تھےاور انہوں نے شریعتِ موسوی میں تغیروتبدل نہیں کیا تھا،اور ان کی فضیلت صرف ان لوگوں پر ہی مراد ہےجوان کے زمانہ میں تھےان پر نہیں جوآئندہ موجود ہونےوالےتھے۔کیونکہ عالم کااطلاق موجودین پر ہوتاہے،لہذااس زمانہ کے لحاظ سے جو موجود تھے انہیں پر عالم کااطلاق ہوا،رہے صحابہ اور تمام امتی وہ نہ اس وقت موجود تھے اور نہ عالمین کالفظ ان کو شامل،لہٰذابنواسرائیل کی امت محمدیہ پر فضیلت لازم نہیں آتی۔
تفاسیرکی ان وضاحتوں سے معلوم ہواکہ بنواسرائیل کو فقط انہیں کے زمانہ میں اقوامِ عالم پر برتری حاصل تھی،سیدنااعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اپنے ترجمہ کے ایک لفظ سے ان سب کا خلاصہ بیان کردیاجب کہ دوسرےترجموں میں بالعموم یہ بات نظرنہیں آتی۔
مقامِ سوم:
حضرت شعیب علیہ السلام اہلِ مدین کی طرف مبعوث ہوئے،بہت سے لوگوں نے آپ کے پیغامِ ہدایت کو قبول نہ کیابلکہ الٹاحضرت شعیب علیہ السلام کویہ مشورہ دیاکہ آپ ہمارامذہب اختیارکرواور اس پر مزیدیہ دھمکی بھی دی کہ اگرتم نے ہمارا مذہب قبول نہ کیاتوہم تمہیں شہر بدر کردیں گے۔مندرجہ ذیل آیت میں اس کا بیان ہے:
قَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ اسْتَکْبَرُوْا مِنْ قَوْمِہٖ لَنُخْرِجَنَّكَ یٰشُعَیْبُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْیَتِنَاۤ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِیْ مِلَّتِنَا
(سورۃ اعراف:88)
اس کی قوم کے متکبرسرداربولےاے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے،یاتم ہمارے دین میں آجاؤ۔
اسی طرح کافروں نے دوسرےانبیائےکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بھی کہاتھا کہ یا تو ہم تمہیں اپنے علاقوں سے ضرورنکال دیں گےیاپھرتم ہمارے مذہب میں آجاؤ۔
آیت:
وَ قَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لِرُسُلِہِمْ لَنُخْرِجَنَّکُمْ مِّنْ اَرْضِنَاۤ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِیْ مِلَّتِنَا
(سورۃ ابراہیم:13)
اورکافروں نے اپنے رسولوں سے کہا:ہم ضرورتمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین پر ہوجاؤ۔
ان دونوں آیتوں کا ترجمہ عام طورپر مترجمین یہ کرتے ہیں کہ:تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤچنانچہ مندرجہ ذیل ترجمے ملاحظہ کیجئے:
یایہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھرآجاؤ۔ (اشرف علی تھانوی)
تم خودہی ہمارے مذہب میں لوٹ آؤگے۔ (ثناءاللہ امرتسری)
یاتم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ (نذیراحمد)
یاپھرہمارےدین میں لوٹ آؤ۔ (وحیدالزماں)
یالوٹ آؤ،ہمارےدین میں۔ (محمودالحسن)
یاتوتمہیں ہماری ملت میں واپس آناہوگا۔ (مودودی)
ان تمام ترجموں سے صاف ظاہر کہ کافروں نے رسولوں کو اپنے مذہب میں لوٹنےکامشورہ دیا تھا،تومطلب یہ ہواکہ انبیائےکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اعلانِ نبوت سے پہلے ان کے مذہب میں داخل تھے۔یعنی انبیائےکرام کافروں میں شریک تھے۔معاذاللہ،یہ سراسرخلافِ واقع اور اہلِ اسلام کے عقیدہ کے قطعاً منافی ہے،عقیدہ یہ ہے کہ کبھی کوئی نبی و رسول کسی کفری عقیدہ میں مبتلانہیں رہے بلکہ وہ توقبل ِاعلانِ نبوت اور اس کے بعد دونوں زمانوں میں کبائرو صغائرسے پاک ہوتے ہیں۔
اسی لیے سیدنااعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ترجمہ فرمایا:تم ہمارے دین پر ہوجاؤ۔دوسری جگہ یوں کیا:تم ہمارے دین میں آجاؤ۔
ان دونوں مقام کے ترجمہ سے عقیدۂ اسلامی پر ذرہ برابرحرف نہیں آرہاہے بلکہ عظمت و عصمتِ انبیائےکرام کی بخوبی حفاظت بھی ہورہی ہے۔
لیکن یہاں ایک علمی سوال ہے کہلتعودنجس کا ترجمہ دوسرے مترجمین نے پھرآنا، لوٹ آنااور واپس آجاناکیاتوکیایہ لغت کے مطابق نہیں اور کیااعلیٰ حضرت کے ترجمہآجانا اور ہوجاناکی بھی کوئی سند ہے۔ بظاہر تویہی معلوم ہوتاہےکہ دیگرمترجمین نے جو ترجمہ کیا ہے وہ لغت کے عین مطابق ہے جب کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لغت مشہورکے موافق نظر نہیں آتااسی چیزکوسمجھنےکے لیے اصول و قواعدِ لغتِ عرب اور مفسرین کی صراحت کی طرف چلتےہیں۔
عربی گرامرکامبتدی طالب علم بھی اس بات سے نحومیر جیسی ابتدائی کتابوں میں واقف ہوجاتا ہے کہعاد افعالِ ناقصہ میں بھی شمار ہوتا ہے،اور اس کا استعمال بمعنیصارخوب ہوتاہے،جیسے:عادزیدغنیازیدغنی ہوگیا۔مطلب یہ ہوا کہعاد جب افعال ناقصہ سےہے اور صارکے معنی میں اس کا استعمال ہوتاہےتوابعادیعودعودًابمعنی صار یصیر صیرورۃہوگا،جس کا معنیہوناہوگا،چونکہصار انتقال کے لیے آتاہےلہذاآجانابھی اس کا معنی ہوگا۔
یہاں سے یہ بات واضح ہوگئی کہ العودہمیشہلوٹنے اورواپس آجانے،کےمعنی ہی میں استعمال نہیں ہوتابلکہ اس کے دوسرےمعنی بھی ہیں، لغت میں بھی اس کی صراحت موجود ہے،چنانچہ لغت کی مشہور و مستند کتاب لسان العرب میں ہے:
عادالشئی یعود عودًاومعادًا أی رجع،وقد یرد بمعنی صار
(لسان العرب،ج:1،ص:326)
عادیعودرجع،کےمعنی میں آتاہے،لیکن اس کا استعمال کبھی صار کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔لہٰذا اب معنی ہوں گے:ایک حال سے دوسرےحال کی طرف منتقل ہونا۔
حدیث شریف میں بھی اس معنی کی صراحت موجودہے،حضورنبی کریمﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ارشادفرمایا:
أعد ت فتانًایامعاذ؟
اےمعاذ!کیاتم لوگوں کو فتنہ میں مبتلاکرنےوالے ہوگئے؟
یہاں عدتبمعنیصرتہے،ایسانہیں کہ حضرت معاذ پہلے بھی ایسےہی فتنہ انگیزتھے اور اب پھراسی حالت کی طرف لوٹ گئے، بلکہ ان کی اس حالت کا بیان ہےکہ پہلے تم لوگوں کو راحت پہنچاتےتھےکیااب ان کو آزمائش میں ڈال رہے ہو۔
آیت ِکریمہ میں بھی یہی معنی مراد ہیں،یعنی کافرانبیائےکرام کو شہربدرکرنےکی دھمکی سنا رہے ہیں یاپھران کے مذہب میں شامل ہوجائیں۔
مفسرینِ کرام نے بھی اس اشکال کودورکرنےکی غرض سے اس معنی کی وضاحت کی ہے۔
تفسیرِبیضاوی اور اس کے حاشیہ شیخ زادہ میں ہے:
حلفواعلیٰ أن یکون أحد الأمرین إما إخراجھم للرسل أو عود ھم إلی ملتھم وھو بمعنی الصیرورۃ لأنھم لم یکونوا علٰی ملتھم قط۔
(اَوْ لَتَعُوْدُنَّ)یوھم أن الأنبیآء کانوا علی ملتھم فی أول الأمرحتی یصح أن یقال: (لَتَعُوْدُنَّ فِیْ مِلَّتِنَا)أجاب عنہ أو لا بأن العود ھنا بمعنی الصیرورۃ إستعمال عاد بمعنی صارکثیر فی کلام العرب:وثانیا بأن الخطاب وإن کان مع الرسل ظاھرا إلا أن المقصود بھذ ا الخطاب کل رسول مع أتباعہ وأصحابہ فغلب أتباع الرسل علی أنفسھم فی حکم العود،فقیل:( اَوْ لَتَعُوْدُنَّ) اذ الظاھر أن الأتباع کانوا قبل ذالك علی دین اولٰئك الکفار، ومع ھذا أن من قال:(اَوْ لَتَعُوْدُنَّ)ھم الکفار ولا یجب أن یکونوا صادقین فی کل ما قالوہ فلعلھم توھموا کون الأنبیآء علٰی ملتھم أوّلًا بناء علی أنھم نشأوا فی بلاد الکفر وما أظھروا مخالفۃ الکفار، فلذلك ظن الکفرۃ أنھم کانوا فی أول الأمر علی دینھم فقالوا:( اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِیْ مِلَّتِنَا)۔
(حاشیہ شیخ زادہ،سورہ ابراہیم:13،ص:150)
یہاں آیت(اولتعود ن)سے اس بات کاوہم ہوتاہےکہ انبیائےکرام پہلے ان کافروں ہی کے مذہب میں تھے۔لہٰذا ان کی بات اسی صورت میں صحیح ہوسکتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاںعودبمعنیصیرورتہے اورعاد کااستعمال بمعنیصارکلامِ عرب میں کثیر الوقوع ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ خطاب یہاں اگرچہ بظاہر پیغمبروں سے ہے مگرمقصود رسولوں کے ساتھ ان کی امتیں اور ان کے اصحاب ہیں، لہٰذا یہاں تغلیباً انبیائےکرام کو مخاطب بنایاگیا، اس لیے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ رسولوں کے متبعین پہلے انہیں کافروں کے دین پر تھے، نیزیہاں کفارکا مقولہ نقل ہواہے۔یعنی(اولتعود ن)کافروں کا قول ہےاور ان کی جہاں اور بہت سی باتیں جھوٹ تھیں اسی طرح یہ بھی جھوٹ، لہٰذاہوسکتاہے کہ انہوں نے اپنے وہم وخیال کے مطابق یہ بات کہی ہو،کیوں کہ انبیائےکرام انہیں کفار کے ملک میں پلے بڑھےاوراعلانِ نبوت سے پہلے ان حضرات نے کفارکی مخالفت بھی نہیں کی۔لہٰذا کفار یہ گمان کربیٹھے کہ یہ لوگ پہلے ہمارے ہی مذہب پر تھے،لہٰذااپنے گمانِ فاسدکی بنیاد پر ان کو مشورہ دینے لگے کہ(اولتعود ن فی ملتنا)یاآپ لوگ ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔
حاشیہ شیخ زادہ میں دوسرے مقام پر سورۂ اعراف میں ہے:
وعاد قد تستعمل بمعنی صار فحینئذ ترفع الاسم وتنصب الخبرفلا تکتفی بمرفوع بل تفتقر الیٰ خبر منصوب فلو کان المعنی ھھنا (اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِیْ مِلَّتِنَا) بعد أن لم تکونوا فیھا لزال الأشکال من غیر احتیاج إلی إعتبار التغلیب۔
(حاشیہ شیخ زادہ سورۃ الاعراف:88،ص:260)
عادکبھی صارکے معنی میں استعمال ہوتاہے،تواس صورت میں یہ اسم کو مرفوع اور خبر کو نصب دے گا،لہٰذافقط مرفوع پر اکتفانہیں کرے گابلکہ اس کو خبرِمنصوب کی بھی احتیاج ہوگی، تو اگریہاں اب اولتعود ن فی ملتناکامعنی أولتصیرن فی ملتناہو،یعنی ہوجاؤ تم ہمارے دین میں،توسرے سے اشکال ہی واردنہیں ہوگا،لہٰذا اب جواب میں تغلیب وغیرہ توجیہات کی ضرورت ہی پیش نہیں آئےگی۔
تفسیرِحدائق الروح والریحان میں ہے:(اولتعودن فی ملتنا)
عاد ھنابمعنی صاروالظرف خبرہ أی:لتصیرن داخلین فی ملتنا، فان الرسل لم یکونوا فی ملتھم قط۔
وفی الخازن:فان قلت: ھذ ایوھم بظاھرہ أنھم کانوا علیٰ ملتھم فی أوّل الأمر حتی یعودوا فیھا۔
قلت: معاذ اللّٰہ،ولکن العود ھنا،بمعنی الصیرورۃ، وھو کثیر فی کلام عرب۔
(تفسیرِحدائق الروح والریحان۔سورۃ ابراہیم:11،ص14/360)
آیتِ کریمہ(اولتعود ن فی ملتنا)میںعادبمعنیصارہےاورظرففی ملتنااس کی خبر،یعنی یاآپ لوگ ہمارے دین میں داخل ہوجاؤ، اس لیے کہ رسول ان کے دین میں پہلے کبھی نہیں تھے۔
تفسیرِخازن میں ہے اس آیت سے بظاہریہ وہم ہوتاہےکہ انبیائےکرام پہلے ان کے مذہب میں داخل تھےجبھی تولوٹنےکامشورہ دے رہے ہیں۔تواس کا جواب صاحب ِخازن نے دیا: معاذاللہ:ایساہرگزنہیں،بلکہ عودیہاں بمعنی صیرورت ہے۔اور یہ کلامِ عرب میں کثیر الاستعمال ہے۔
تفسیر ِبحرِمدیرمیں ہے:
حلفوا لیکونن أحد الأمرین،إما إخراج الرسل من د یارھم، أو عود ھم إلی ملتھم، والعود ھنا بمعنی الصیرورۃ،لأنھم لم یکونوا علی ملتھم، کما تقدم فی قصۃ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام
(سورۃ ابراہیم:13،ص:362)
کافروں نے حلف اٹھایاکہ دوچیزوں میں سے ایک ضرورہوگی،یاتوان رسولوں کو شہربدر کیا جائےگا۔ یا یہ ان کے مذہب میں آجائیں۔ اورعودیہاں بمعنی صیرورت ہے،اس لیے کہ انبیائےکرام ان کے دین میں کبھی نہیں تھے،جیساکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں گذرا۔
تفسیرِروح البیان میں ہے:
عاد بمعنی صار والظرف خبر أی لتصیرن فی أھل ملتنا فان الرسل لم یکونوا فی ملتھم قط۔
(سورۃ ابراہیم:13،ص،4/428)
تفسیر ِروح البیان میں ہے:
والمراد من العود الصیرورۃ والإنتقال من حال إلی أخری وھو کثیر الإستعمال بھذا المعنی،فیندفع ما یتوھم من أن العود یقتضی أن الرسل علیھم السلام کانوا۔وحاشاھم۔فی ملۃ الکفرقبل ذلك۔
(سورۃ ابراہیم:13،ص،3/288)
اور عود سے مراد صیرورت اور ایک حال سے دوسرےحال کی طرف انتقال ہے اور اس معنی میں کثیرالاستعمال ہے،لہذاوہ وہم دفع ہوگیا کہ عود یعنی لوٹنا اس بات کا متقاضی ہے کہ انبیائےکرام اس سے پہلے کفرکی حالت میں تھے۔معاذاللہ۔
تفسیرِفتح القدیرمیں ہے:
والعود ھنا بمعنی الصیرورۃ لعصمۃ الأنبیاء عن أن یکونوا علی ملۃ الکفرقبل النبوۃ وبعد ھا ۔
(سورۃ ابراہیم:13،ص3/123)
عودیہاں صیرورۃ کے معنی میں ہے ،اس لیےکہ انبیائے کرام علیہ التحیتہ والسلام قبل اعلان نبوت اور اس کے بعد دونوں زمانوں میں کفروشرک سے معصوم ہوتے ہیں۔
تفسیرِبحرمحیط میں ہے:
العود بمعنی الصیرورۃ
(سورۃ ابراھیم:13،ص:400)
عود صیرورت کے معنی میں ہے۔
تفسیرِجلالین اور صاوی میں ہے:
(اَوْ لَتَعُوْدُنَّ) تصیرن،( فِیْ مِلَّتِنَا) دیننا۔ دفع بذلك ما یقال:ان العود یقتضی أنہ سبق لھم التبس بملتھم مع أن الرسل معصومون من ذلك،فأجاب المفسر:بأن المراد الصیرورۃ،أی:لتصیرن داخلین فی ملتنا۔
(صاوی علی جلالین،ص:2/226)
(أولتعودن)کامعنی ہے یاہوجاؤ ہمارےدین میں،اس سے اس اعتراض کاجواب دینا ہے کہ لوٹنااس بات کو چاہتاہے کہ وہ ان کے دین پر تھے۔حالانکہ اللہ کے رسول اس سے معصوم ہوتے ہیں،لہذا مفسراس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہعودبمعنی صیرورت ہے یعنی تم ہمارےدین میں داخل ہوجاؤ۔
تفسیرِماتریدی میں ہے:
قولہ: (لتعودن) لیس أنھم کانوافیھاوترکوھا،ولکن علی إبتداء الد خول فیھا علی ما ذکرنا۔
(ص6/374)
یہاں لتعودن بایں معنی نہیں کہ یہ حضرات پہلے کفرمیں مبتلاتھے(معاذاللہ)پھراس کو ترک کردیا،بلکہ یہاں ابتداءِ دخول مرادہے۔
تفسیرِ ارشادالعقل السلیم میں ہے:
والعود إما بمعنی مطلق الصیرورۃ أو بإعتبار تغلیب المؤمنین علی الرسل۔
(سورۃ ابراہیم:13،ص3/183)
عودیاتومطلق صیرورت کے معنی میں ہےیاپھرباعتبارتغلیب یہ حکم لگایاگیا۔
تفسیرِزادالمسیرمیں ہے:
والثانی ان المعنی:لتصیرن الی ملتنا،فوقع العود علی معنی الابتداء،
کما یقال:قد عاد علیّ من فلان مکروہ،أی قد لحقنی منہ ذالک، وان لم یکن سبق منہ مکروہ۔
(سورۃ الاعراف:88،ص3/177)
دوسری توجیہ یہ ہے کہ تم ہمارے دین پرہوجاؤ،چنانچہ عود کے معنی ابتداء کسی حال پر ہوجانا ہیں،جیسے کہاجاتاہے:فلاں کی جانب سے مجھے یہ ناپسندیدہ چیزلاحق ہوئی،اگرچہ اس سے قبل کبھی کوئی،پسندیدہ چیزلاحق نہ ہوئی ہو۔
ان تمام تفاسیرکی روشنی میں یہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ سیدنااعلیٰ حضرت امام احمدرضاقدس سرہ کا ترجمہ ان تفاسیر کے عین مطابق ہےاور آپ نے محتاط قول کوہی اپنایا جس سے انبیائے کرام کی شانِ عصمت میں کسی طرح کا شبہ بھی نہیں ہوسکتا۔آپ کے ترجمہ کی خوبیاں اتنی نہیں کہ مجھ جیساہیچ مداں شمارکرسکے،مختصر جامع اور آخری بات وہی ہے جو محدثِ اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمائی :
علمِ قرآن کا اندازہ اگرصرف اعلیٰ حضرت کے اس ترجمہ سے کیجئےجو اکثرگھروں میں موجود ہے اور جس کی کوئی مثال سابق نہ عربی زبان میں ہے نہ فارسی میں ہے اور نہ اردومیں، اور جس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پرایساہے کہ دوسرالفظ اس جگہ لایانہیں جاسکتا۔